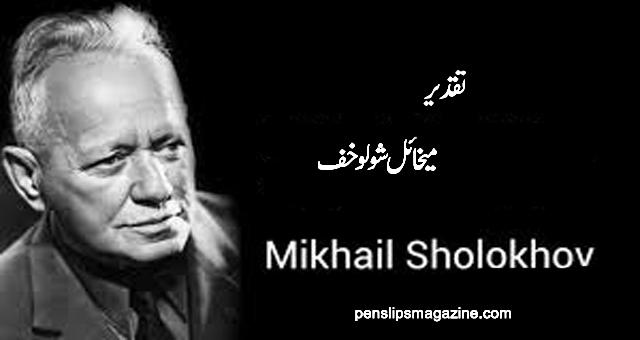
تقدیر ۔۔۔ میخائل شولوخف
تقدیر
میخائل شولوخف
دُوسری جنگِ عظیم ختم ہوئے ایک سال ہوا تھا اور دریائے ڈان کے کنارے موسمِ بہار میں گاڑی لے جانا مشکل ہو گیا تھا کیونکہ مارچ کے آخر میں بحیرہ ازوف کی جانب سے گرم ہوائیں چلتی تھیں اور دریائے ڈان کے کناروں سے برف ہٹا کر انہیں برہنہ کر دیتی تھیں جبکہ برف پگھل کر منہ زور سیلاب بن جاتی تھی جس سے سڑکوں پر آمد و رفت معطل ہو جاتی۔
اس انتہائی غیر موزوں موقعے پر مجھے بوکانووسکایا کے گاؤں کا سفر کرنا پڑگیا۔ سفر تو اتنا ذیادہ نہ تھا، یہی ۶۰ کلو میٹر ہو گا لیکن ان حالات میں ازحد کٹھن ہو گیا تھا۔ میں اور میرا دوست صبح دم روانہ ہوئے۔ ہمارے صحت مند اور خوش خوراک گھوڑے بھاری بھرکم کوچ کھینچنے کیلئے تیا ر تھے۔ ہماری گاڑی کے پہیئے برف اور ریت میں دُھرے تک دھنسے ہوئے تھے اور گھنٹہ بھر میں گھوڑوں کے کاندھوں اور ٹانگوں کے درمیان سے جھاگ اُڑنے لگی۔ پھر صبح کی خوشگوار ہوا اور گھوڑوں کے پسینے کی بُو نے باہم مل کر ایک مدہوش کر دینے والی تیز خوشبو کا مرکب ایجاد کر دیا۔
جہاں گھوڑوں کا چلنا ازحد دشوار ہو جاتا وہاں ہم گاڑی سے اُتر آتے اور پیدل چلنا شروع کر دیتے۔ اس برف میں چلنا بھی کافی دُشوار تھا۔ سڑک کے کنارے کی برف ابھی تک نسبتاً سخت تھی اور چمک رہی تھی۔ ہمیں دریائے یلانکا کے پایاب پتن تک کا ۳۰ کلو میٹر کا فاصلہ طے کرنے میں چھے گھنٹے لگ گئے۔ موخووسکی کے دیہہ میں، جہاں دریا بالکل چھوٹا سا تھا اور گرمیوں میں تو عموماً خُشک رہتا تھا، اب یہ صوتحال تھی کہ دُور تک پانی اور بڑھے ہوئے پودوں کی وجہ سے ایک دلدل سی بن گئی تھی جسے ہم نے چپٹے پیندے کی ایک کشتی میں سوار ہو کر عبور کیا جبکہ گاڑی واپس گھر بھجوا دی۔ دوسری جانب ایک فارم کے چھپر کے نیچے ایک پرانی جیپ، جو موسمِ سرما میں عموماً کھڑی رہتی تھی، آج ہماری منتظر تھی۔ میں اور ڈرائیور تھوڑے وہم کے ساتھ اس کھٹارے میں سوار ہو گئے جبکہ میرا دوست پیچھے کنارے پر، سامان کے ساتھ ہی رہا۔ اب دریا عبور کرنے کیلئے ہم نے لکڑی کے تختوں پر گاڑی ڈال دی تو تختوں میں سوراخوں سے پانی کے فوارے چھوٹ پڑے جنہیں ہم نے لکڑی کے ڈاٹ ٹھونس کر یا ہاتھوں سے دبا کر روکا تا آنکہ ہم ایک گھنٹے کی جدوجہد کے بعد دوسرے کنارے پہنچ گئے۔ ’’اگر یہ پُرانا ٹب پانی میں ٹوٹ کر بکھر نہ گیا تو اُمید ہے کہ میں ایک دو گھنٹے میں تمہارے دوست کو لے کر آپہنچوں گا‘‘ جیپ ڈرائیور نے چپُو اُٹھاتے ہوئے مجھ سے کہا اور کشتی کی طرف چلا گیا۔
گاؤں دریا سے کچھ فاصلے پر تھا جس پر ابھی تک وہی خموشی اور سکوت طاری تھا جو کہ موسمِ سرماکے باعث نقل مکانی کے بعد ہوتا ہے، جو کہ بہار کی شروعات تک رہتا ہے۔ پانی کے اوپر چلتی ہوئی ہوا مرطوب تھی جس میں آلڈر (علاقائی درخت جس سے چمڑا رنگنے کا مواد حاصل ہوتا ہے) کے گلے سڑے درختوں کی سڑاند بھی شامل تھی، البتہ کچھ دور کے گلِ یاس کی باس سے اٹے گھاس کے وسیع میدانوں سے ہوا کے جھونکے اس مٹی کی بھینی بھینی خوش بُو لا رہے تھے جو کہ ابھی ابھی برف کی قید سے آزاد ہوئی تھی۔ پاس ہی ریت پر ایک ٹوٹا ہوا، لکڑی کا جنگلا پڑا تھا، میں جا کر اس پر بیٹھ گیا اور جیکٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا کہ سگریٹ نکال کر سلگائی جائے لیکن یہ محسوس کر کے سخت کوفت ہوئی کہ سگریٹ کی ڈبیا بھیگ چکی تھی۔ دراصل دریا عبور کرتے ہوئے گدلے پانی کے ایک بڑے چھینٹے نے مجھے اور میری جیکٹ کو بھگو دیا تھا لیکن اس وقت ہم خود کو ڈوبنے سے بچانے کی کوششوں میں لگے تھے جس وجہ سے میرا فوری دھیان سگریٹ کی طرف نہیں گیا۔ اب مجھے اپنی بے احتیاطی پر افسوس ہوا اور میں نے بھیگا ہوا پیکٹ جیب سے نکالا اور بھیگے ہوئے بھورے بھورے سگریٹ ایک ایک کر کے جنگلے پر سوکھنے کے لئے رکھنے لگا۔
دوپہر ہو چکی تھی اور سورج مئی کے کسی دن کی طرح گرمی برسا رہا تھا، میرا خیال تھا کہ سگریٹ جلد سُوکھ جائیں گے۔ اب اتنی گرمی پڑی کہ مجھے اس بات پر بھی تشویش ہونے لگی کہ میں خواہ مخواہ موٹا فوجی ٹراؤزر اور جیکٹ پہن کر سفر پر نکلا تھا۔ اگرچہ یہ سال کا پہلا گرم دن تھا لیکن پھر بھی یہاں بالکل اکیلا، تنہائی اور سکوت میں بیٹھنا بہت اچھا لگ رہا تھا، خود کو اس تنہائی کے حوالے کر کے، اپنے سر سے فوجی ٹوپی اُتار کر کشتی رانی کی مشقت میں بھیگنے والے بالوں کو خشک کرنا اور ہلکے نیلے آسمان میں تیرنے والے نیلے بادل کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا ایک خوشگوار احساس تھا۔
اسی اثنأ میں مَیں نے دیکھا کہ گاؤں کی آخری جھونپڑی سے ایک شخص نکل کر سڑک پر آیا جس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ بھی اس کا ہاتھ پکڑ کر آرہا تھا۔ میرے اندازے کے مطابق یہ بچہ پانچ یا چھے برس سے ذیادہ کا نہیں تھا۔ وہ بھاری قدموں سے پتن کی جانب چل رہے تھے لیکن جیپ کو دیکھ کر میری طرف مڑ آئے۔ لمبا تڑنگا شخص سیدھا میری طرف آیا اور مجھے مخاطب کیا، ’’ ہیلو دوست!‘‘ میں نے بھی ’’ہیلو‘‘ کہہ کر اُس کے بھاری بھرکم ہاتھ سے ہاتھ ملایا۔ وہ شخص بچے کی طرف جھکا،
’’بیٹا، انکل کو سلام کہو!، یوں سمجھو،
یہ بھی تمہارے ابا کی طرح ڈرائیور ہیں۔۔۔ ہم بھی لاری چلاتے تھے ناں؟ اب یہ وہاں
تک گاڑی لے جاتے ہیں‘‘ اس نے بچے سے کہا۔
بچے نے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں آسمان کی طرح صاف
اور روشن تھیں۔ وہ مسکرایا اور اپنا گلابی سا ٹھنڈا ہاتھ مجھ سے ملایا۔ میں نے
آہستہ سے اُس کا ہاتھ ہلایا اور پوچھا،
’’سردی لگ رہی ہے نوجوان؟‘‘
وہ بچگانہ اعتماد سے میرے قریب ہو کر بولا
’’لیکن میں جوان تو نہیں ہوں انکل! میں تو ایک لڑکا ہوں
اور مجھے سردی نہیں لگ رہی، دراصل میرے ہاتھ ٹھنڈے اس لئے ہیں کہ میں برف کے گولے
بناتا رہا ہوں‘‘
لڑکے کا باپ پیٹھ سے تھیلا اُتار کر دھپ سے میرے پاس بیٹھ گیا،
’’یہ صاحبزادہ جو میرا ہمسفر ہے، ایک
مستقل وبال ہے۔ یہ خود بھی تھکا ہے اور مجھے بھی تھکا دیا ہے اس نے! آپ نے لمبے
لمبے ڈگ بھرنا شروع کردیا تو یہ دوڑنا شروع کر دے گا۔ بس اس کے ساتھ قدم ملا کر
چلو، جہاں مجھے ایک قدم اٹھانا تھا، وہاں تین تین قدم اٹھانے پڑتے ہیں لہٰذا یہ
سفر خرگوش اور کچھوے کی دوڑ بن جاتا ہے۔ پھر اس پر کڑی نظر بھی رکھنا پڑتی ہے،
ادھر آپ کی نگاہ چُوکی، ادھر یہ دوڑ کے قائق میں جا بیٹھا اور پانی میں نکل گیا
یا پھر برف کے گولے بنا کر قلفی کی طرح چوسنے لگ گیا! ناں بھئی ناں! اس کے ساتھ
سفر، اور وہ بھی پیدل، یہ کسی آدمی کے بس کا روگ نہیں ‘‘
اُس نے کہا، پھر لمحہ بھر کو توقف کیا۔
’’آپ سناؤ دوست! مالک کا انتظار کر رہے
ہو؟‘‘
اُس نے پوچھا لیکن میں اسے یہ نہیں بتانا چاہ رہا تھا کہ
میں ڈرائیور نہیں ہوں لہٰذا میں نے جواب دیا۔
’’لگتا تو یہی ہے‘‘
’’کیا وہ دوسری طرف سے آنے والا ہے؟‘‘
’’ہاں!‘‘
’’کیا یہ کشتی جلد آ جائے گی؟‘‘
’’نہیں تقریباً دو گھنٹے تک آئے گی‘‘
’’بہت دیر ہے پھر تو۔ چلو فکر مت کرو، مجھے بھی کوئی جلدی نہیں ہے۔۔۔ میں راہ سے گذر رہا تھا کہ تمہیں دیکھا تو سوچا کہ کوئی اپنا ڈرائیور بھائی بیٹھا دھوپ سینک رہا ہے، سوچا چلو مل کر سگریٹ پیتے ہیں۔ اکیلے سگریٹ پینا اور اکیلے مرنا، کون سا فرق ہے ان میں! ٹھیک کر رہے ہو! سگریٹ پی رہے ہو! کیا بھیگ گئے؟ بھیگا ہوا تمباکو تو بیمار گھوڑے کے موافق ہے، دونوں بے کار! چلو اب میرے سگریٹ چکھو!‘‘
اس نے کہا۔ اس نے اپنے
پتلے خاکی پتلون کی جیب سے ایک ریشمی تھیلا نکالا اور اسے کھولا۔ تھیلے پر کچھ
ایسے الفاظ کڑھے ہوئے تھے:
’’ لیبے ڈینسکایا سیکنڈری اسکول کے ایک طالب علم کی طرف
سے اپنے وطن کے پیارے سپاہی کے لئے!‘‘
ہم نے گھریلو کاشت شدہ تمباکو کے سگریٹ پیے اور کافی دیر تک ہم میں سے کسی نے کوئی بات نہ کی۔ میں ابھی اس خیال میں تھا کہ اس سے پوچھوں کہ وہ اس لڑکے کے ہمراہ کہاں جا رہا ہے اور ان خراب سڑکوں پر کس مجبوری کے تحت سفر پہ نکلا ہے لیکن اُس نے پہلے ہی سوال داغ دیا۔
’’تُم نے جنگ میں حصہ لیا؟‘‘
’’ہاں، ساری جنگ میں!‘‘
’’اگلی صفوں میں؟‘‘
’’ہاں!‘‘
’’اچھا ! دوست میں نے تو بہت مصائب جھیلے ہیں۔۔۔ بلکہ
بہت سے بھی ذیادہ۔۔۔‘‘
اس نے اپنے بڑے بڑے سنولائے ہوئے ہاتھ گھٹنوں پر ٹکائے اور کندھے ڈھلکا دئیے۔ میں نے جب اسے ایک طرف سے دیکھا تو مجھے بہت عجیب محسوس ہوا۔ کیا آپ نے کبھی ایسی آنکھیں دیکھی ہیں جن میں راکھ اُڑ کر پڑ جائے اور وہ ایک ناقابلِ بیان درد سے گذر رہی ہوتی ہیں تو ایسے میں اُن آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنا بھی کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اس نئے دوست کی آنکھیں کچھ ایسی تھیں!
اس نے جنگلے سے ایک خشک
تنکا توڑا اور ریت پر ایک مہمل سا خاکہ بنانے لگا، ایک منٹ بعد وہ گویا ہوا۔
’’میں اکثر رات بھر سو نہیں سکتا، میں اندھیرے میں
گھورتا ہوں اور سوچتا ہوں ’یہ تُم نے کس کیلئے کیا؟ زندگی کیلئے؟ کیوں اس طرح
تڑپایا مجھے؟ کس جُرم کی سزا دی؟‘ اور مجھے کوئی جواب نہیں ملتا خواہ اندھیرا ہو
یا دن کی روشنی، مجھے کوئی جواب نہیں ملتا اور کبھی نہیں ملے گا!‘‘
پھر اس نے ایک دم بچے کو چمکارتے ہوئے کہا،
’’جاؤ بیٹا، نیچے جا کر دریا کے پاس کھیلو ! لیکن اپنے
پاؤں مت بھگو لینا!‘‘
اس دوران جب ہم دونوں خموشی سے سگریٹ پی رہے تھے، میں نے غور کیا تو باپ اور بیٹے کی وضع قطع میں ایک واضح سا فرق نظر آیا جو مجھے کچھ عجیب سا لگا۔ بچہ سادہ لیکن صاف اور عمدہ کپڑوں میں ملبوس تھا۔ بچے کا لمبی اسکرٹ کا کوٹ،اس کے سلیقے سے لگے رفو، جرابیں اور عمدگی سے بچے کو پہنائے گئے ننھے ننھے بُوٹ واضح طور پر کسی سگھڑ عورت کے ہنر کی عکاسی کر رہے تھے۔ لیکن بچے کے باپ کی وضع بالکل مختلف تھی۔ اس کے جیکٹ پر مختلف جگہوں پر بے ڈھنگے رفو کے نشانات تھے اور اسکی خاکی پتلون پر بے سلیقگی سے پیوند لگے ہوئے تھے جو کہ کسی مردانہ ہاتھ کی ’’کاریگری‘‘ لگ رہے تھے۔ اس نے نئے فوجی بوٹ پہن رکھے تھے لیکن اس کی اونی جرابوں پر جگہ جگہ سے کیڑا کھا جانے کی وجہ سے سوراخ نمایا ں تھے۔ لگتا تھا کہ ان جرابوں کو کبھی کسی عورت نے چھوا تک نہیں تھا۔
’’شائد رنڈوا ہے یا پھر میاں بیوی کے
مابین کوئی گڑ بڑ ہے‘‘
میں نے سوچا۔
اُس نے اپنے بچے کو نیچے کی طرف دوڑتے ہوئے دیکھا، پھر کھانسا اور ایک بار پھر گویا ہوا۔ اب میں نے اس کی بات نہایت توجہ سے سُنی۔
’’شروع میں تو میری زندگی بالکل عام سی
رہی۔۔۔‘‘ اس نے اپنی کہانی آغاز کی۔۔۔
میں صوبہ ورونزہ کا رہنے والا ہوں جہاں میں سن ۱۹۰۰ میں پیدا ہوا۔ خانہ
جنگی کے دوران میں سرخ فوج کے کیکویڈ ڈویژن میں تھا۔ ۱۹۲۲ والے قحط میں مَیں
کوبان سے نکلا اور پھر کولکوں کے لئے ایک سانڈ کی طرح کام کیا اور مشقت کی۔ اور
مشقت نہ کرتا تو زندہ کیسے رہتا؟ پیچھے گھر میں میرا سارا خاندان، ماں، باپ اور
بہن فاقوں سے مر گئے اور میں اکیلا رہ گیا۔۔۔ رشتہ دار بھی کوئی نہ تھے! پھر ایک
سال بعد میں کوبان کو لوٹا، اپنا گھر بار فروخت کیا اور ورونزہ چلا گیا۔ پہلے میں
نے بڑھئی کا کام کیا، پھر ایک کارخانے میں جا کر مستری کا کام سیکھ لیا۔ کچھ ہی
عرصہ بعد میں نے شادی کرلی۔ میری بیوی ایک یتیم خانے میں پلی بڑھی تھی اور ایک
اچھی خاتون تھی، خوش مزاج، ملنسار اور ہمہ وقت شادمان۔ وہ خوبصورت بھی تھی اور اس
لحاظ سے اُس کا اور میرا جوڑ نہ تھا۔ اسے خبر تھی کہ بچپن اس پر کس طرح بیتا تھا
اور میں تو کہوں گا اس نے اس کے کردار پر گہرا اثر ڈالا تھا۔ خیر میری نظر میں اس
جیسی خوبصورت عورت دُنیا میں کوئی نہ تھی۔۔۔ اور کوئی نہ ہوگی!
میں اکثر کام سے تھکا
ہارا آتا تھا تو شدید غصے یا ناگوار موڈ میں ہوتا تھا لیکن اس نے کبھی ناگواری کا
جواب غصے سے نہیں دیا۔ وہ اتنی شریف اور پرامن طبیعت کی عورت تھی کہ وہ مجھے خوش
کرنے کیلئے کوئی اچھی سے اچھی کھانے کی چیز بنا رکھتی تھی، حتیٰ کہ تب بھی جب اتنی
استطاعت بھی نہ ہوتی۔ میں اُسے دیکھتا تھا تو دل ہلکا ہو جاتا تھا اور پھر میں
اُسے بانہوں میں لے کر کہتا، ’’ارینہؔ! معاف کرنا میں نے تم سے سختی کی! دراصل آج
کام میں بہت بُرا دن گزرا!‘‘ اور پھر گھر میں یکسر سکون ہو جاتا اور میرا ذہن
مطمئن ہو جاتا تھا۔ اور کام کیا تھا دوست! صبحدم میں گولی کی طرح بستر سے نکلتا
تھا، فیکٹری جاتا اور پھر جو کچھ کرنے کو ملتا، وہ رات گئے تک جاری رہتا۔ اس کے
لئے ایک زیرک لڑکی ہی بیوی کے طور پر ضروری تھی۔
کبھی کبھی تنخواہ کی ادائیگی کے دن میں لڑکوں کے ہمراہ
شراب پینے چلا جاتا اور رات کو لڑکھڑاتے ہوئے گھر آتا۔ لیکن میں اُن دنوں اتنا
قوی اور صحتمند تھا کہ بہت سی پی لینے کے بعد بھی ازخود گھر آجاتا تھا۔ لیکن
تمہیں پتا ہے، آخر۔۔۔ کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ۔۔۔ مجھے بھی ہاتھوں اور گھٹنوں
کے بل یہ فاصلہ طے کرنا پڑتا۔ لیکن ایسے میں بھی میں کبھی غل غپاڑا اور گالم گلوچ
نہیں کی۔ میری ارینہؔ مجھ پر ہنس دیتی لیکن اس امر کا احتیاط ضرور کرتی کہ میں
بُرا نہ مان جاؤں۔ وہ میرے بوٹ اُتار تی اور سرگوشی کرکے کہتی، ’’آج آپ پلنگ پر
دیوار کی جانب سوئیے گا تاکہ آپ رات کو نیند میں بستر سے لڑھک کر زمین پر ہی نہ
آ پڑیں‘‘ میں دھڑام سے اخروٹوں سے بھرے کسی تھیلے کی طرح بستر پر گرتا اور مجھے
ہر شے اپنے ارد گرد تیرتی نظر آتی۔ نیند کی آغوش میں بھی مجھے محسوس ہوتا کہ وہ
نرمی سے میرا سر دبا رہی ہوتی اور بڑے پیار سے کچھ کہہ رہی ہوتی تھی جس کی وجہ
مجھے پتا ہے؛ اسے میری حالت پر افسوس ہو رہا ہوتا تھا۔
صبح کو، وہ مجھے فیکٹری کے اوقات کار سے دو گھنٹے پہلے جگا دیتی تاکہ میں پوری طرح ہوش میں آ جاؤں۔ اسے پتا تھا کہ پینے کے بعد میں کچھ کھاتا نہیں تھا لہٰذا وہ مجھے کھیرے کا اچار یا کوئی اور ایسی چیز، واڈکا کے ایک گلاس کے ساتھ، کھانے کو دیتی اور نرمی سے کہتی؛ ’’آندرے! اب اتنی ذیادہ مت پینا!‘‘ جو شخص ہم پر اتنا بھروسہ کرے ہم کیوں نہ اس کی بات کا پاس رکھیں۔ میں واڈکا پی کر خموشی سے اسکا شکریہ آنکھوں ہی میں اور ایک بوسے کے ساتھ ادا کرتا اور ایک سیدھے سادے میمنے کی طرح کام پہ چلا جاتا۔ اگر وہ ایسی حالت میں، جب میں نے پی رکھی ہوتی، مجھے غصہ دلاتی تو یقین جانو کہ میں دوبارہ پی کر آتا۔ یہ اکثر ان گھرانوں میں ہوتا ہے جہاں احمق بیویاں ہوتی ہیں۔ میں نے بہت دیکھا ہے ایسا ہوتا ہوا۔
پھر بچوں کی آمد شروع ہو گئی۔ پہلے بیٹا ہوا، پھر دو بیٹیاں ہوئیں۔ اس کے بعد میں اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گیا اور میں اپنی ساری تنخواہ اپنی بیوی کو لا کر دیتا۔ اب میرے خاندان کی ایک معقول نفری تھی جس کی وجہ سے میں شراب نوشی کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ چھٹی والے دن بیئر کا ایک گلاس پی کر گزارا کر لیتا تھا۔
۱۹۲۹ میں مجھے گاڑیوں میں دلچسپی پیدا ہوئی۔ میں نے ڈرائیونگ سیکھ کر لاری چلانا شروع کردیا اور پھر فیکٹری جانا چھوڑ دیا کہ مجھے ڈرائیونگ میں لُطف آنے لگا تھا۔ اور پھر دس برس کیسے گزرے، اس کا پتا بھی نہ چلا کہ دس برس گزر گئے۔ یہ ایک خواب کی مانند تھا۔ دس سال کتنا عرصہ ہے، کسی چالیس سے ذیادہ عمر کے آدمی سے پوچھو کہ سال کا عرصہ کتنی تیزی سے کھسک جاتا ہے، آپ کو پتا چلے گا کہ اسے واقعی اندازہ نہیں۔ ماضی گھاس کے ایک وسیع و عریض میدان کی مانند ہے جو کہ پیچھے دُور کہیں دھندلکے میں چھپ چکا ہوتا ہے۔ آج صبح میں اس سے گزر رہا تھا اور یہ واضح تھا کہ لیکن اب بیس کلو میٹر آگے آگیا ہوں تو اس پر دھند چھا گئی ہے اور مجھے گھاس، درختوں، ہل لگی زمینوں اور باغیچوں میں کوئی فرق نہیں لگ رہا، دھند نے سب برابر کر دیئے ہیں۔
ان دس سالوں میں مَیں نے دن رات کام کیا۔ میں نے کافی رقم کمالی اور اب ہمارا میعارِ زندگی کئی مزدوروں سے بہتر ہو گیا۔ بچے ہمارے لئے خوشی اور مسرت کا ایک خزانہ تھے۔ تینوں پڑھائی میں بھی بہت اچھے تھے بلکہ سب سے بڑا اناطولی ؔ تو ریاضی میں اتنا لائق تھا کہ ایک بار ماسکو کے ایک اخبار میں اس کا اعزاز بھی چھپا تھا۔ یہ لیاقت اُسے کس ورثے میں ملی، یہ تو میں کچھ نہیں بتا سکتا دوست، لیکن مجھے اس پر بہت فخر تھا۔
دس سال میں ہم نے اتنی کچھ رقم بچا لی تھی کہ ہم نے جنگ سے پہلے دو کمروں، ایک سامان کے کمرے اور ایک برآمدے کا چھوٹا سا گھر بنا لیا۔ ارینہؔ نے دو بکریاں بھی خرید لیں۔ اب اور کیا چاہیئے تھا ہمیں؟ بچوں کیلئے دودھ میسر تھا، سر پر چھت تھی، تن پر کپڑ اتھا، پاؤں میں جوتے تھے لہٰذا سب اچھا تھا۔ البتہ ایک کمی تھی، وہ یہ کہ گھر کا محل وقوع کچھ مناسب نہ تھا۔ میں نے گھر بنانے کیلئے جس جگہ پلاٹ خریدا، وہ ایک طیارہ ساز فیکٹری کے بہت قریب تھی۔ اگر میرا گھر کہیں اور ہوتا تو میری زندگی بڑی مختلف ہوتی۔
اور پھر جنگ چھڑ گئی۔ اگلے روز مجھے بھی بلاوے کا پروانہ موصول ہو گیا اور اس سے اگلا دن فوج میں رپورٹ کرنے کا تھا۔ میرے بیوی بچوں۔۔۔ ارینہؔ، اناطولیؔ (اور بیٹیوں) نستیکاؔ اور الیوشکاؔ نے مجھے الوداع کہا۔ بچوں نے اچھے طریقے سے الوداع کہا، دونوں لڑکیوں نے ایک دو آنسو بہائے، اناطولیؔ نے بس ایک جھرجھری سی لی گویا اسے سردی لگ رہی ہو۔ وہ اب سترہ سال کا ہونے کو تھا۔ لیکن میری ارینہؔ۔۔۔ میں نے گزشتہ سترہ سالہ رفاقت میں ایسا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ رات بھر وہ میرے شانے پہ سر رکھ کے روئی تھی اور میری قمیص بھگو دی، دن ہوا تو اس نے پھر وہی کام کیا۔ ہم سب اسٹیشن پر پہنچے اور ارینہؔ کی حالت پہ مجھے اتنا ترس آ رہا تھا کہ میں آنکھ بھر کر اس کے چہرے کی طرف نہ دیکھ سکا۔ اس کے ہونٹ سوج چکے تھے اور بال چادر سے باہر بکھرے ہوئے تھے اور اس کی آنکھیں ایسے گھور رہی تھیں جیسے وہ حواس باختہ ہو۔ افسران نے ریل پر سوار ہونے کا حکم دیا تو وہ میرے گلے لگ کے یوں جھول گئی اور ایسے کانپ گئی جیسے کسی درخت کو آرے سے کاٹا جا رہا ہو۔ دوسری خواتین اپنے شوہروں کے ساتھ گپیں ہانک رہی تھیں اور میری بیوی ایک شاخ سے لٹکے پتے کی طرح میرے گلے سے لگی تھی اور یوں کانپ رہی تھی کہ اس کی زبان سے کوئی لفظ ادا نہیں ہو رہا تھا۔
’’خود پہ قابو رکھو ارینہؔ‘‘ میں نے پیار
سے کہا ’’ کم از کم جانے سے پہلے مجھے کچھ کہو!‘‘
اور وہ سسکتے ہوئے بس اتنا ہی کہہ سکی،
’’آندرے، میرے پیارے آندرےؔ! ہم۔۔۔ ہم اب اس دُنیا
میں۔۔۔ کبھی ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکیں گے!‘‘
ایک میں تھا کہ میرا دل اس کے لئے ترحّم سے پھٹا جا رہا تھا اور وہ تھی کہ ایسی باتیں کہہ رہی تھی۔ اسے یہ سمجھنا چاہیئے تھا کہ میرے لئے اس سے جُدا ہونا کتنا مشکل تھا۔ میں بھی تو کسی تقریب پہ نہیں جا رہا تھا۔ مجھے خود پہ اختیار نہ رہا اور خود پہ غصہ آگیا۔ میں نے اُس کے دونوں ہاتھ جھٹک کر اُس کو خفیف سا دھکا دے کر خود سے علیحدہ کر دیا۔ یہ خفیف دھکا تو میرے لئے تھا کہ میں تو ایک سانڈ کی طرح قوی تھا؛ وہ تین قدم پیچھے تک لڑکھڑا گئی، پھر چھوٹے قدموں کے ساتھ بازو پھیلائے میری طرف بڑھی تو مَیں اُس پر چلّایا،
’’ یہ طریقہ ہے الوداع کہنے کا؟؟؟ مجھے
مرنے سے پہلے ہی گاڑ دینا چاہتی ہو؟؟؟‘‘
لیکن پھر میں نے اُسے بانہوں میں لے لیا کیونکہ اب اُسکی
حالت بہت بُری تھی۔
اس کی رُندھی ہوئی آواز سُنائی دی اور پھر وہ خاموش ہو گیا۔ اس کے جذبات بھی ابلاغ کر رہے تھے۔ میں نے اُس کو ایک طرف سے دیکھا تو مجھے اُس کی مُردہ، راکھ ہوتی ہوئی آنکھوں میں کوئی آنسُو نظر نہ آیا۔ وہ افسردگی سے سر نیہوڑائے بیٹھا تھا۔ اس کے بھاری بھرکم ہاتھ اس کے پہلوؤں کی طرف ڈھلک گئے اور ہلکے سے کانپنے لگے اور ساتھ ہی اس کی ٹھوڑی اور مضبوط ہونٹ بھی تھرتھرانے لگے۔
’’دوست ان باتوں کو دل پر مت لو!‘‘
میں نے آہستہ سے کہا
لیکن اُس نے شائد کچھ نہیں سُنا۔ بمشکل اپنے جذبات پر قابوُ پاتے ہوئے اُس نے
دوبارہ نحیف آواز میں کہا؛
’’میں اپنی موت تک، زندگی کی آخری سانس تک خود کو اُس
ایک دھکے پر معاف نہیں کروں گا!‘‘
وہ دوبارہ کافی دیر تک خاموش رہا۔ اس نے ایک سگریٹ بنانے کی کوشش کی لیکن اخباری کاغذ اسکی انگلیوں میں کھل گیا اور سارا تمباکو اس کے گھٹنوں پر گر گیا۔ آخر کوشش کر کے وہ ایک بھدا سا سگریٹ بنا سکا اور چند لمبے کش لینے کے بعد دوبارہ گلا صاف کر کے گویا ہوا۔
میں نے خود سے ارینہؔ کو جُدا کیا پھر اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لے کر بوسہ دیا۔ اس کے ہونٹ برف کی طرح سرد تھے۔ میں نے بچوں کو الوداع کہا اور ریل کی جانب دوڑا اور پھلانگ کر اس کے پائیدان پر چڑھ گیا۔ ریل آہستہ سے چلی تو دوبارہ میرے اہلِ خانہ کے سامنے سے مجھے لے کر گزری۔ میں نے اپنے مسکین بچوں کو ایک دوسرے سے لپٹ کر میری طرف الوداع کیلئے ہاتھ ہلاتے ہوئے دیکھا، جو مسکرانے کی کوشش بھی کررہے تھے لیکن مسکرا نہیں پا رہے تھے۔ ارینہؔ نے اپنے ہاتھوں کو سینے پہ مضبوطی سے جکڑ رکھا تھا۔ اس کے ہونٹ چاک کی طرح سفید تھے اور وہ کچھ سرگوشی کررہی تھی۔ وہ میری طرف تکے جارہی تھی اور یوں آگے کی طرف جھکی ہوئی تھی جیسے ہوا کے مخالف سمت چل رہی ہو۔ اور باقی تمام زندگی میں جب بھی مَیں نے اسے یاد کیا، اسی حالت میں وہ میری یادداشت میں آئی۔۔۔وہ سینے پر بندھے ہاتھ، وہ سفید ہونٹ، اور وہ آنسوؤں سے بھری، پھٹی پھٹی آنکھیں۔۔۔ اور اسی حالت میں مَیں اُسے خوابوں میں بھی دیکھتا ہوں۔ اب بھی جب سوچتا ہوں کہ میں نے کیوں اُس کو یوں دھکا دیا تو ایسے لگتا ہے جیسے ایک کُند چاقو میرے دل میں اُتر رہا ہے۔
ہمیں یوکرائن میں اپنی اپنی یونٹوں میں بھیج دیا گیا۔ مجھے ایک تین ٹن کا ٹرک دیا گیا جس پر مَیں محاذِ جنگ پر گیا۔ تو یہاں یہ بتانا تو بے جا ہو گا کہ جنگ کیسے ہوئی اور اس کی شروعات کیسی تھیں کیونکہ تُم جانتے ہو دوست اور تُم نے یہ جنگ خود دیکھی ہے۔ مجھے گھر سے کئی خطوط ملے لیکن میں نے کچھ ذیادہ خطوط گھر نہیں بھیجے۔ کبھی کبھی میں لکھتا تھا اور یہی کہتا تھا کہ یہاں سب اچھا ہے اور ہمیں کم ہی لڑنا پڑتا ہے۔ جس وقت ہم پسپائی اختیار کر رہے ہوتے، تب بھی میں یہی لکھتا تھا کہ ہم اپنی قوتوں کو مجتمع کررہے ہیں۔ اس کے علاوہ کیا لکھتا؟ بُرا وقت تھا اور میں ذیادہ خطوط لکھنے کا قائل نہ تھا۔ میں اُن ساتھیوں کو سخت بُرا بھلا کہتا جو اپنی بیویوں اور محبوباؤں کو بلاوجہ روزانہ خط لکھتے اور کیا کیا رونے روتے، ’’اُف خُدایا، یہ کٹھن گھڑی ہے، اُف میں مارا جاؤں گا‘‘ اور وہ اس طرح لکھے جاتے، اُلّو کے پٹھے شکوے کرتے، ہمدردی حاصل کرنے کیلئے بلبلاتے لیکن یہ نہ سوچتے کہ وہ بیچاری خواتین اور بچے بھی تو انہی کی طرح بُرے حالات میں ہیں۔ آخر ہم نے کیوں مُلک کا بوجھ اپنے کاندھوں پر اُٹھا رکھا ہے؟ اور ہمارے بیوی بچوں کو بھی یہ بوجھ اُٹھانے کیلئے کیسے کاندھے چاہیئں؟ لیکن وہ نہ رُکے اور لگے رہے ایسے خطوط لکھنے کو!اور جب ایسا تھڑ دِلا سپاہی ایسا درد بھرا خط لکھتا ہے تو وہ ایک کام کرتی ہوئی عورت کا حوصلہ تباہ کر کے اسے بیکار بنا دیتا ہے۔ اس طرح کے خطوط پڑھنے کے بعد وہ بیچاری خود کو کس طرح سنبھالتی ہو گی! لیکن تُم مرد ہو ہی اسی لئے اور اسی لئے فوجی ہو کہ ہر حال میں حوصلہ بلند رکھو! اگر تمہارے اندر ایک مرد کی جگہ ایک عورت کی سی روح ہے تو جاؤ، عورتوں کی طرح اسکرٹ پہن کر گائے کا دودھ دوہنا شروع کر و یا چقندروں کی کیاری میں گوڈی کرو! کیونکہ محاذ پر تُم ایسوں کی کوئی ضرورت نہیں!
لیکن میں ایک سال بھی محاذ پر نہ لڑ سکا۔ میں دوبار زخمی ہوا۔ دونوں بار معمولی زخم آئے، ایک بار بازو میں اور دوسری بار ٹانگ میں۔ پہلا زخم ہوائی جہاز کی گولی سے لگا جبکہ دوسرا توپ کے گولے کا ٹکڑا لگنے سے ہوا۔ جرمنوں نے میری گاڑی میں اُوپر سے اور ایک سمت سے چھید کرڈالے لیکن میں خوش قسمتی سے بچ گیا۔ لیکن ہمیشہ خوش قسمت نہیں رہا کیونکہ ایک بار میں حقیقت میں بدقسمت واقع ہوا جب میں مئی ۱۹۴۲ میں لوزووینکی کے مقام پر جنگی قیدی بن گیا۔ بڑی بے تُکی صورت حال تھی۔ جرمن ہمارے توپخانے کی ایک بیٹری پر شدید حملہ کررہے تھے جس میں ۱۲۲ ملی میٹر دہانے کی ہاؤٹزر توپیں تھیں لیکن ان کا گولہ بارود ختم ہونے کو تھا۔ میری لاری کو توپ کے گولوں سے بھرا گیا جس میں مَیں نے خود بھی کافی مشقت کی حتیٰ کہ میری وردی پسینے سے میرے جسم پہ چپک گئی۔ ہمیں آگے بڑھنا تھا کیونکہ دشمن قریب تر ہو رہا تھا جبکہ دائیں جانب ٹینکوں کی آواز آ رہی تھی اور بائیں طرف فائرنگ ہو رہی تھی۔
’’سوکولیؔف! جاؤ گے؟‘‘
کمپنی کمانڈر نے مجھ سے پوچھا۔ پوچھنے کی کیا ضرورت تھی،
میرے ساتھی مارے جارہے تھے اور میں کیا ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ سکتا تھا؟
’’سر آپ کیا بات کر رہے ہیں! میں کیوں نہیں جاؤں گا!‘‘
’’پھر لپک پڑو! پہنچو!‘‘
میں نے کہا تو افسر نے فوراً حُکم دے دیا۔
میں ٹرک میں سوار ہوا۔ اس سے پہلے میں نے اس طرح کبھی ڈرائیونگ نہیں کی تھی اور آج مجھے پتا تھا کہ میں نےگاڑی میں کوئی کھُرپے، بیلچے نہیں بھر رکھے اور مجھے محتاط رہنا پڑے گا لیکن جب ہمارے سپاہی دشمن سے نہتے لڑنے پر مجبور تھے اور پور ا راستہ توپخانے کی شدید گولہ باری کی ذد میں تھا تو میں کتنا محتاط رہ سکتا تھا۔ چھے کلو میٹر کا فاصلہ طے کرنے کے بعد ہی میں اپنی منزل کے کافی قریب پہنچ گیا تھا، مجھے سڑک سے اُتر کر اُس بیٹری تک جانا تھا لیکن کیا دیکھتا ہوں کہ سڑک کے دونوں طرف ہمارے پیادے کے سپاہی کھیتوں میں پیچھے کی طرف دوڑے آرہے تھے اور توپوں کے گولے ان کے آس پاس پھٹ رہے تھے۔ میں پیچھے بھی نہیں مُڑ سکتا تھا لہٰذا پوری رفتار سے اپنی مطلوبہ منزل۔۔۔ توپخانے کی اُس بیٹری کی طرف گامزن رہا جو کہ بمشکل ایک کلومیٹر کے فاصلے پر تھی۔ لیکن دوست! میں وہاں تک نہ پہنچ سکا! یہ کوئی دُور مار توپ کا گولہ تھا جو میری گاڑی کے قریب گر کر پھٹا۔ میں نے کوئی دھماکے کی آواز نہیں سُنی بلکہ یوں لگا کہ میرا سر ایک دھماکے سے پھٹ گیا ہے، اس کے سوا مجھے کچھ یاد نہیں!میں زندہ کیسے رہا اور وہاں کتنی دیر پڑا رہا، مجھے اس کی مطلق خبر نہیں۔ میں نےآنکھیں کھولیں لیکن اُٹھ نہ سکا، میرا سر یوں کانپ رہا تھا جیسے مجھے بخار ہو۔ سب کچھ سیاہ نظر آ رہا تھا اور مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے بائیں کاندھے میں کوئی ٹوٹی ہوئی شے رگڑ کھا رہی ہو اور باقی جسم یوں درد کررہا تھا جیسے مجھے کسی نے شدت سے مارا پیٹا ہو۔ کافی تگ و دو کے بعد میں اُٹھ کھڑا ہوا، مگر مجھے کچھ خبر نہ تھی کہ میں کہاں ہوں اور میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میری یادداشت بالکل معطل ہو گئی۔ لیکن میں زمین پر پڑا رہنے سے گھبرا رہا تھا۔ میں خوفزدہ تھا کہ شاید اب میں کبھی نہیں اُٹھ سکوں گا لہٰذا میں اُٹھا اور آندھی میں کھڑے پیڑ کی طرح دائیں بائیں جھولتا ہوا چلنے لگا۔ جب میں اُٹھا اور اپنے ارد گرد دیکھا تو میرے دل میں ایسے ٹیس اُٹھی جیسے کسی نے اسے سلائی میں پرو لیا ہو۔ میں توپخانے کے جو گولے لے جارہا تھا، اب وہ میرے گرد بکھرے پڑے تھے۔ پاس ہی میرا ٹرک بھی پڑا تھا جس کے پہیئے آسمان کی طرف تھے۔ اور میرے عقب میں لڑائی ہو رہی تھی۔ ہاں! میرے عقب میں! جونہی مجھے اس کا اندازہ ہوا کہ دُشمن کی صفیں آگے نکل گئی ہیں اور میں اپنے عقب سے کٹ کے اب دشمن کے عقب میں ہوں تو میں زمین پر یوں گرا جیسے کوئی درخت کٹ کر گرتا ہے۔ میں ایک جنگی قیدی بن چکا تھا!
دوست جب آپ کو یقین ہو کہ آپ نے کوئی فاش غلطی نہیں کی تو آپ کیسے باور کر لیں گے کہ آپ واقعی قیدی ہو گئے ہیں اور کسی ایسے ساتھی کو یہ سب کچھ سمجھانا بھی آسان نہیں جو خود اس تجربے سے نہ گُزرا ہو۔
خیر میں وہیں لیٹا پڑا رہا اور تھوڑی دیر میں ہی میں نے ٹینکوں کی گڑگڑاہٹ سُنی۔ چار جرمن ٹینک میرے پاس سے پوری رفتار سے گزر کر اس سمت کو چلے گئے جس سمت سے میں آیا تھا۔ کیا احساسات ہوں گے میرے اُس لمحے؟! پھر چند ٹریکٹر توپیں کھینچتے ہوئے وہاں سے گزرے، پھر گشتی لنگر، پھر پیادہ سپاہ جو ایک کمپنی سے ذیادہ نہ ہو گی۔ میں اپنی آنکھ ذرا سی کھول کر انہیں دیکھتا اور پھر مٹی میں اپنا سر دبا لیتا۔ اس نے میری حالت مزید بُری کر دی۔
میرے اندازے کے مطابق جب تمام لوگ گزر گئے تو میں نے اُٹھایا، چھے مسلح سپاہی لگ بھگ سو قدم کے فاصلے سے گزررہے تھے۔ جونہی میں نے اُنہیں دیکھا، وہ سارے سڑک سے اُتر کر میری طرف آ گئے۔ ’اچھا، تو یہ رہی!‘ میں نے سوچا اور اُٹھ بیٹھا، پھر سیدھا کھڑا ہو گیا کیونکہ میں زمین پہ لیٹے ہوئے نہیں مرنا چاہتا تھا۔ اُن میں سے ایک مجھ سے چند قدم کے فاصلے پر رُکا اور جھٹکے سے اپنی ہلکی مشین گن کاندھے سے اُتار کر مجھ پر تان لی۔ انسان بھی کیا کمال کی شے ہے! میرے دل پہ اس لمحے ذرہ برابر بھی خوف یا لرزہ طاری نہ ہوا بلکہ میں نے اس کی طرف دیکھ کر سوچا کہ اب چھوٹا سا برسٹ چلے گا، لیکن کہاں مارے گا؟ سر میں یا چھاتی کے آر پار؟ گویا وہ میرے جسم کے جس حصے پر گولی چلائے گا، مجھے اس سے کوئی واسطہ ہی نہ ہو۔
وہ دشمن، نوجوان سپاہی تھا، اچھے قدوقامت اور سیاہ بالوں والا لیکن اس کے ہونٹ دھاگے کی طرح پتلے تھے اور اس کی آنکھوں سے حقارت ٹپک رہی تھی۔ وہ مجھے گولی سے اُڑا دینے کیلئے دوسری بار سوچنے والا بھی نہیں لگتا تھا تاہم اُس نے بندوق اوپر کر لی جبکہ میں خموش، اُسکی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ دوسرا، جو کہ شاید کوئی کارپورل وغیرہ تھا اور اُس سے بڑا لگ رہا تھا، اُسے ایک طرف دھکیل کر میری طرف بڑھا۔ وہ اپنی زبان میں کچھ بڑبڑایا اور میری دائیں کہنی کو موڑا۔ وہ میرے مضبوط پٹھے دیکھ رہا تھا۔ ’’اوہو!‘‘ اس نے کہا اور مغرب کی طرف، سڑک کی جانب چلنے کا اشارہ کیا گویا مجھے حکم دے رہا تھا کہ چلو، اور جرمنی کیلئے مشقت کرو! کوئی بخیل انسان تھا، حرامزادہ!
لیکن سیاہ بالوں والے کی نظر میرے نئے بوٹوں پر پڑ گئی۔ اُس نے مجھے بوٹ اُتارنے کا اشارہ کیا۔ میں زمین پر بیٹھا اور بوٹ اُتار کر اس کے حوالے کر دیئے جو اس نے فوراً اُچک لئے۔ ساتھ ہی میں نے جرابیں اُتار کر اُسے دیں تو وہ غصے میں گالیاں بکنے لگا اور اس نے بندوق تان لی جبکہ اس کے دوسرے ساتھی قہقہہ لگا کر ہنس پڑے۔ وہ لوگ چلے گئے لیکن سیاہ بالوں والے نے دو تین دفعہ مُڑ کر مجھے سخت غصے کے عالم میں کسی بھیڑیئے کے بچے کی طرح دیکھا گویا اُس نے میرے جوتے نہ چھینے ہوں بلکہ میں نے اُس کے جوتے غصب کر لئے ہوں۔
میں سڑک پر چل پڑا اور مغرب کا رُخ کر لیا۔۔۔ ایک قیدی کے طور پر۔ لیکن اب میں ذیادہ سے ذیادہ ایک کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل سکتا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے میں نے پی رکھی ہو؛ میں سیدھا آگے چلتا تو یوں لگتا جیسے کوئی مجھے اطراف سے دھکیل رہا ہو۔ پہلے میں اپنے ساتھیوں کی ایک ٹولی سے جا ملا، پھر ایک دستے سے اور بالآخر اپنی سپاہ کے اس ڈویژن سے جو پورا ہی جنگی قیدی ہو گیا تھا۔ دشمن کے دس مشین گن بردار سپاہی ہم پر پہرے دار مقرر تھے۔ دستے کے سامنے چلنے والا سپاہی میری طرف آیا اور کچھ بات کئے بغیر میرے سر میں بندوق سے ایک ضرب لگائی تاکہ میں اگر لڑکھڑا کر گر جاؤں تو وہیں گولی مار کر مجھے ختم کر دے لیکن میرے ساتھیوں نے مجھے سہارا دیا اور مجھے باقی بھِیڑ میں چھپا لیا اور اسی طرح کافی آگے تک لے کر چلے۔ مجھے تھوڑا ہوش آیا تو ایک ساتھی نے میرے کان میں سرگوشی کی،
’’خُدا کے لئے گرنا مت! جب تک ذرہ برابر
بھی قوت ہے، چلتے رہو! گرو گے تو یہ لوگ تمہیں مار دیں گے!‘‘
اور پھر جب تک مجھ میں ذرا سی بھی تاب و تواں رہی، میں
کسی طرح چلتا رہا۔
سرِ شام جرمنوں کے سنتریوں کی کمک آگئی۔ ایک لاری میں مزید مشین گن بردار سپاہی آگئے جو ہمیں پہلے سے ذیادہ رفتار سے لے کر چلے۔ شدید زخمی، جو کہ چل نہیں سکتے تھے، سڑک پر ہی گولیوں سے اُڑا دیئے گئے۔ دو قیدیوں نے اسی اثنا ٔ میں بھاگنے کی کوشش کی لیکن چاندنی رات میں تو میل بھر تک دیکھا جا سکتا تھا، یہ دونوں مارے گئے۔ نصف شب کا عمل ہو گا کہ ہم ایک گاؤں میں پہنچے جو کہ آدھا جل کر خاکستر ہو چکا تھا۔ ہمیں ایک تباہ شدہ گنبد والے چرچ میں اکٹھا کردیا گیا۔ ہمیں یہ رات چرچ کے فرش پر گزارنا تھی۔ کسی کے پاس بڑا کوٹ تھا، نہ کمبل، کچھ لڑکوں نے تو صرف وردی کی قمیصیں پہن رکھی تھیں کیونکہ وہ نان کمیشنڈ افسران تھے اور اپنے عہدے چھپانے کی خاطر اُنہوں نے اپنے کوٹ اُتار دیئے تھے۔ توپ خانے کا عملہ بھی اپنے کوٹ اُتار کر اپنے کام میں لگا تھا لہٰذا وہ بھی اسی طرح آئے تھے۔ کسی پاس زمین پر بچھانے کو بھی کچھ نہ تھا۔
اس رات شدید بارش ہوئی اور ہم بُری طرح بھیگ گئے۔ چرچ کی چھت توپ کا گولہ لگنے سے تباہ ہو چکی تھی جبکہ اس کے ’چَھروں‘ نے دیوار کو چھلنی کر دیا تھا لہٰذا پورے گرجا میں کہیں خشک جگہ نہ تھی حتیٰ کہ قربان گاہ کی انگیٹھی بھی پانی سے بھر گئی تھی۔ ہم رات بھر باڑے کی بھیڑوں کی مانند اس گرجا میں کھڑے رہے۔ نصف شب کے کافی بعد کسی نے میرے بازو کو تھام کر سوال کیا،
’’کامریڈ! زخمی ہو؟‘‘
’’تُم کیوں پوچھ رہے ہو دوست؟‘‘ میں نے کہا۔
’’میں ڈاکٹر ہوں اور تمہاری مدد کر سکتا ہوں‘‘
اُس نے جواب دیا تو میں نے بتایا کہ میرا بایاں کاندھا
کچھ چٹخنے کی آواز نکالتا ہے اور بُری طرح سُوج گیا ہے۔ اس نے مجھے کوٹ اور قمیص
اُتارنے کا حُکم دیا۔ میں نے اُتار دیئے تو اُس نے اپنی پتلی انگلیوں سے میرے
کاندھے کو ٹٹولنا شروع کر دیا۔ اس سے مجھے شدید درد ہو اتو میں بلبلا اُٹھا۔
’’تُم ڈاکٹر ہو کہ قصاب؟، جہاں ذیادہ درد ہو رہا ہے،
وہیں ذیادہ دبا رہے ہو؟ بے درد جہنمی!‘‘
لیکن ڈاکٹر خموشی سے میرا کاندھا ٹٹولتا رہا، پھر سختی
سے بولا،
’’تمہارا کام ہے خموش رہنا! مجھ سے ایسی باتیں نہ کرو
بلکہ مضبوط ہو جاؤ، اصل درد تو اب ہو گا!‘‘
اس کے بعد اس نے میرے بازو کو یوں مروڑا کہ سچ مچ میں
میرے چودہ طبق روشن کردئیے۔ جب میرے حواس بحال ہوئے، میں نے اُس سے پوچھا،
’’کیا کررہے ہو ظالم نازی! میرا بازو ٹوٹ گیا ہے اور تُم
اسے یوں مروڑ رہے ہو؟‘‘
وہ ہنسا اور جواب دیا،
’’مجھے اندیشہ تھا کہ میں جس طرح تمہارے بائیں بازو کو مروڑ ررہا تھا، تُم دائیں ہاتھ سے مجھے گھونسا دے مارو گے لیکن تُم تو کمال تحمل اور برداشت والے ہو۔ تمہارا بازو ٹوٹا نہیں، بس ذرا کاندھے سے نکل گیا تھا، اب میں نے درست جگہ بٹھا دیا ہے، دیکھو درد میں کوئی فرق نہیں آیا؟‘‘
واقعی میرے شانے کا درد ختم ہو چکا تھا، میں نے ڈاکٹر کا شکریہ ادا کیا اور وہ اندھیرے میں مزید زخمیون کا پوچھنے لگا کہ اگر کوئی زخمی ہے تو وہ اسکی مدد کرے۔ اس اندھیرے میں قید ہونے کے باوجود بھی وہ شخص اپنے عظیم فریضے میں مصروف ہو گیا۔
یہ بڑی کٹھن رات تھی۔
اُنہوں نے ہمیں ضروری حاجات کیلئے بھی باہر نہ جانے دیا۔ گارڈ کمانڈر نے کہا تھا
کہ وہ ہمیں باہر نہیں جانے دے سکتے۔ بد قسمتی سے ایک عیسائی لڑکے کو پیشاب کی شدید
حاجت محسوس ہوئی تو پہلے اس نے ضبط کیا لیکن آخر ِ کار رو پڑا،
’’میں ایک مقدس جگہ کو کیسے ناپاک کردوں؟‘‘
اس نے فریاد کی تو کچھ ساتھی ہنس پڑے، کچھ نے اسے خوب گالیاں دیں، کسی نے اس کو سمجھایا اور کسی نے اس کو مزید ستانے والی باتیں کیں۔ وہ گڑگڑاتا رہا۔
’’میں عیسائی ہوں، ایک مومن عیسائی، میں کیا کروں ساتھیو!‘‘
اس نے بالآخر زور زور سے دروازہ بجانا شروع کردیا کہ اسے باہر جانے دیا جائے۔کچھ دیر کے بعد اسے جواب ملا۔ جواب کیا تھا، جرمن مشین گن سے گولیوں کی ایک بوچھار جس سے وہ عیسائی اپنے تین مزید ساتھیوں سمیت مارا گیا۔ ایک جوان شدید زخمی ہوا جس نے بعد ازاں صبح کے وقت دم توڑ دیا۔
ہم نے اپنے مُردہ ساتھیوں کو ایک کونے میں ڈال دیا اور اپنے انجام کے بارے میں سوچنے لگے کہ آغاز تو بہت بُرا ہوا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد ہم نے سرگوشیوں میں گفتگو شروع کر دی اور پوچھنے لگے،
’’کہاں کے رہنے والے ہو؟ کس طرح قیدی ہوئے؟‘‘
ایک ہی کمپنی یا پلاٹون کے لوگ ایک دوسرے کو اندھیرے میں ہی بُلانے لگے اور میں نے اپنے پاس ایک آواز سُنی۔
’’پلٹون کمانڈر صاحب! کل جب ہمیں مزید آگے لے جانے سے پہلے یہ لوگ قطاروں میں کھڑا کر کے افسران، اشتراکیوں اور یہودیوں کی شناخت کی کوشش کریں گے تو خود کو مت چھپانا! تمہارا کیا خیال ہے کہ اپنا کوٹ اُتار کر تم خود کو سپاہی ظاہر کرلو گے؟ میں تمہاری خاطر مصائب نہیں سہہ سکتا اور میں سب سے پہلے تُم پر انگلی رکھوں گا! مجھے پتا ہے تُم اشتراکی ہو ! تُم نے مجھے پارٹی میں شامل کرنے کی کوشش کی تھی! اب اس کا جواب خود دینا!‘‘
یہ میرے بائیں جانب بیٹھا ہوا ایک سپاہی تھا۔ اُس سے آگے کوئی نوجوان افسر بیٹھا تھا جس کا جواب مجھے سُنائی دیا۔
’’کرزنیفؔ! مجھے تُم پر ہمیشہ شک رہتا تھا اور خاص طور پر تب تم میری نظروں میں مشکوک ہو گئے تھے جب تم نے ان پڑھ ہونے کا بہانہ کر کے پارٹی میں شمولیت سے انکار کیا تھا لیکن میں نے یہ توقع کبھی نہیں کی تھی کہ تم ایک غدار ثابت ہو گے! تم چودہ سال کی عمر تک اسکول جاتے رہے ہو! ایسا ہی ہے ناں؟‘‘
’’ہاں! تو کیا ہوا؟؟؟‘‘
دوسرے نے عامیانہ سے لہجے میں کہا۔ وہ کافی دیر تک خاموش
رہے، پھر پلاٹون کمانڈر، جس کی آواز اب میں پہچان سکتا تھا، دھیمی آواز میں
بولا،
’’کامریڈ کرزنیفؔ! ایسا مت کرو!‘‘
دوسرا جواباً ہنس دیا۔
’’تمہارے کامریڈ صفوں کی دوسری جانب رہ گئے ہیں، میں
تمہارا کامریڈ نہیں ہوں! میں تُم پر اُنگلی رکھوں گا! مجھے اپنی جان بہرحال عزیز
ہے!‘‘
کرزنیفؔ نے کہا۔
اس کے بعد ان کی گفتگو ختم ہو گئی لیکن اس غدار کی
کمینگی نے مجھے بے سکون کردیا۔
’’نہیں!!‘‘
میں سوچنے لگا۔
’’حرامزادے کرزنیفؔ! میں تمہیں کبھی اپنے کمانڈر سے
غداری نہیں کرنے دوں گا! تم اس گرجا سے اپنے پیروں پر نہیں نکلو گے! تمہیں ٹانگوں
سے گھسیٹ کر باہر پھینکا جائے گا!‘‘
اب آہستہ آہستہ روشنی
ہونے لگی اور اس کا چہرہ نظر آنے لگا، وہ بڑے سے بھاری بھرکم چہرے والا تھا اور
اپنے سر کے نیچے ہاتھ ٹِکا کر سویا ہوا تھا اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا چپٹی ناک
والا لڑکا ایک قمیص میں ملبوس اپنے بازوؤں کو گھٹنوں پر لپیٹے بیٹھا تھا اور اس
کا رنگ بالکل زرد ہو چکا تھا۔
’’یہ نوجوان اس زناور کو اکیلا نہیں سنبھال سکے گا، اسے
میں اکیلا ختم کروں گا‘‘
میں نے سوچا۔
’’آپ پلٹون کمانڈر ہیں؟‘‘
میں نے اس نوجوان کا بازو چُھو کر اس سے سوال کیا۔ اس نے
اثبات میں سر ہلایا اور کچھ نہ کہا۔
’’کیا یہی شخص ہے جو آپکی نشاندہی کرنا چاہتا ہے؟؟‘‘
میں دوبارہ پوچھا تو اس نے اثبات میں سر ہلایا۔
’’اچھا‘‘ میں نے کہا۔ ’’تو آپ اسکی ٹانگیں مضبوطی سے
پکڑیں تاکہ یہ لاتیں نہ جھاڑ سکے، اور تیزی سے!‘‘
یہ کہتے ہی میں اس غدار کے سینے پر چڑھ گیا اور پلک جھپکتے ہی اس کے گلے پر پوری قوت سے اپنی انگلیاں دبائیں اور اسے چلاّ نے کا وقت بھی نہ مل سکا۔ کچھ دیر تک میں نے اسے اپنے نیچے دبائے رکھا اور پھر جب چھوڑا تو ایک اور غدار اپنی لٹکتی ہوئی زبان کے ساتھ ختم ہو چکا تھا۔
اس کے بعد مجھے اتنی کراہت محسوس ہوئی کہ مجھے ہاتھ دھونے کی شدید حاجت محسوس ہونے لگی گویا میں نے کوئی انسان نہیں بلکہ ایک سانپ اپنے ہاتھ سے مارا ہو۔ زندگی میں پہلی بار میں نے کسی کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا تھا اور وہ بھی اپنا سپاہی تھا! بلکہ اپنا کیوں کہوں وہ اپنا ہرگز نہیں تھا؛ غدار، دُشمن سے بھی بدتر! میں اُٹھا اور پلاٹون کمانڈر سے کہا،
’’کامریڈ! ا اُٹھیں یہاں سے! چرچ میں کافی جگہ ہے بیٹھنے کی‘‘
صبح وہی ہو جو غدار کرزنیفؔ نے کہا تھا اور ہمیں چرچ کے بہر قطاروں میں کھڑا کیا گیا جہاں مشین گن بردار سپاہیوں کے حلقے میں جرمن ایس ایس(شٹز شٹافل کا مخفف۔ ہٹلر کا مخصوص دستہ جو خفیہ کارروائیوں اور سویلین و فوجی نوعیت کی خصوصی قتل و غارت، باالخصوص ہولو کاسٹ کی وجہ سے تاریخ میں بدنام ہے: مترجم) کے افسران نے خطرناک لوگوں مثلاً کمیونسٹوں، یہودیوں اور افسران کو علیحدہ کرنے کیلئے ہماری شناخت پریڈ کی لیکن انہیں کچھ نہ ملا۔ انہیں کوئی ایسا چغل خور بھی نہ ملا جو کسی کی نشاندہی کرتا کیونکہ ہم میں سے نصف کمیونسٹ اور باقی بڑی تعداد افسران کی تھی۔ دو سو کی سپاہ سے وہ صرف چار فوجی علیحدہ کر سکے۔ ایک یہودی اور باقی تین سپاہی تھے۔ ان روسیوں کی مصیبت یہ تھی کہ سب کے بال سیاہ اور گھنگریالے تھے۔ ایس ایس کا افسر اُن روسیوں کے پاس گیا اور پوچھا،
’’یہودی؟‘‘
اور بغیر اُن کا جواب سُنے حُکم دیا،
’’ایک قدم آگے نکل آؤ!‘‘
ان بے چاروں کو قتل کردیا گیا اور ہمیں مزید آگے بڑھنے کا حُکم مل گیا۔ پھر پلاٹون کمانڈر، جس کے ساتھ مل کر میں نے اُس غدار کو قتل کیا تھا، پوزنانؔ تک میرے ساتھ رہا۔ سفر کے پہلے دن سے وہ میرے پاس آجاتا اور گاہے بگاہے میرا ہاتھ دباتا اور ہم سفر پر گامزن رہتے۔ پوزنانؔ کے مقام پر ہم الگ ہوگئے۔ ہوا یوں کہ میں جب سے قیدی ہوا تھا، فرار کے بارے سوچ رہا تھا۔ میں کسی یقینی کامیابی کے چکر میں تھا جو کہ پوزنانؔ پہنچنے تک مشکل تھا جہاں ہمارے لئے قیدی کیمپ قائم کیا گیا تھامجھے کبھی یقینی حد تک موزوں موقع نہ مل سکا لیکن پوزنانؔ میں ایک موقع ضرور ملا۔ ماہ مئی کے آخر میں ہمیں کیمپ سے باہر ایک جنگل میں لے جایا گیا جہاں ہمیں اپنے اُن ساتھیوں کی قبریں بنانا تھیں جو کہ اس ماہ پیٹ کی بیماریوں میں مبتلا ہو کر مر گئے تھے۔ ایک قبر کھودتے ہوئے میں نے دیکھا کہ ہم پر تعینات گارد کے دو سنتری کھانا کھا رہے ہیں جبکہ ایک دھوپ میں بیٹھا انگھ رہا ہے، تو میں نے بیلچہ رکھا اور ایک جھاڑی کے پیچھے چھُپ گیا۔ اس کے بعد میں نے مغرب کی طرف رُخ کیا اور ناک کی سیدھ میں بھاگنا شروع کردیا۔
انہوں نے اسی وقت میرا تعاقب شروع نہیں کیا۔ مجھے اس ایک دن میں لگ بھگ چالیس کلو میٹر کا فاصلہ طے کرنا تھا اور اس کا اندازہ مجھے بھی نہیں تھا تاہم اس کا کوئی فائدہ نہ ہوا اور چوتھے روز اس موذی کیمپ سے کافی دور اُن لوگوں نے مجھے گرفتار کر لیا۔ ایک کھیت میں شکاری کتوں نے مجھے سونگھ سونگھ کر ڈھونڈ نکالا۔
شام مجھے ایک کھلی جگہ میں پڑی اور یہ جگہ کیمپ سے بمشکل تین کلو میٹر دور تھی۔ میں دن کی روشنی میں چلنے سے ڈرتا تھا اور دن بھر چھپ کرلیٹا رہا۔ میں نے کچھ دانے مروڑ کر اپنی جیب میں ٹھونس لئے تاکہ مزید کچھ خوراک کا بندوبست ہو جائے لیکن اسی اثنأ میں مجھے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں اور موٹرسائیکلوں کا شور سُنائی دیا۔ میں سیدھا لیٹا رہا اور اپنا چہرہ اپنے بازوؤں سے چھپا لیا تاکہ کُتے میرے چہرے کو نہ کاٹیں۔ وہ جوں جوں نزدیک آرہے تھے، میرا دل ڈوبتا جا رہا تھا۔ بالآخر وہ آپہنچے اور آن کی آن میں میرا لباس چیر کر تار تار کر ڈالا اور مجھے مادرزاد برہنہ کر دیا۔ اُنہوں نے مجھے گھسیٹا اور پھر ایک بڑے کُتے نے اپنے آگے کے پنجے میرے سینے پر رکھ کر مجھ پر پیشاب کردیا لیکن اس نے مجھے کاٹا نہیں۔
کیا بتاؤں دوست، جرمن
قید میں جو قیامت مجھ پر اور میرے ساتھیوں پر گزری، اس کا بیان کرنے لگوں تو کلیجہ
منہ کو آتا ہے۔۔۔ دم گھٹنے لگتا ہے۔۔۔
قید کے دو سالوں میں وہ مجھے جس طرح ایک جگہ سے دوسری
جگہ منتقل کرتے رہے، میرا اندازہ ہے کہ میں آدھے جرمنی کا پانی تو پی چکا ہوں گا۔
سیکسونیؔ میں مجھے سلیکیٹ کے ایک کارخانے میں کام کرنا پڑا، روہرؔ میں کوئلے کی
کان میں مزدوری کی اور بویریاؔ میں کھدائی کا کام کیا۔ ترنجنؔ میں کچھ وقت گزارا
اور کسے معلوم کہ جرمنی کا کون سا کونا ہے جس پہ میرے لڑکھڑاتے قدم نہ پڑے ہوں گے۔
ہر جگہ پر مختلف مناظر تھے لیکن جرمنوں کا ظلم اور غارت گری ہر جگہ ایک جیسی ہی
تھی۔ یہ حرامزادے ہمیں اس طرح ذدوکوب کرتے تھے کہ جیسے کسی نے کبھی جانوروں کو بھی
نہ مارا ہو گا۔ وہ ہمیں گھونسے جَڑتے، لاتوں سے مارتے، ربڑ کے کوڑوں سے ہماری کھال
اُدھیڑ کے رکھ دیتے اور اگر ہاتھ آتیں تو لوہے کی سلاخیں تک ہم پر برساتے اور
بندوقوں کے بٹ اور ڈنڈوں کا تو ذکر ہی کیا کرنا!
وہ ہمیں فقط اس لئے
مارتے تھے کہ ہم روسی تھے یا شاید ہم ابھی تک ذندہ تھے یا پھر اس لیے کہ ہم ان کے
غلام ہو کر کام کررہے تھے۔ وہ فقط اس وجہ سے بھی ہم پر تشدد کر سکتے تھے کہ اگر ہم
دیکھنے میں اُنہیں اچھے نہ لگیں، ہمارے چلنے میں کوئی لغزش ہو یا پھر ہم اُن کے
حکم پر درست طریقے سے مُڑ نہ سکے ہوں۔ وہ اسی طرح تشدد کرتے کہ گویا کسی روز اس
ذدوکوب کی ہی تاب نہ لاتے ہوئے ہم مر جائیں گے اور ہمارا دم اپنے بہتے ہوئے خون
میں گھُٹ جائے گا۔ اُن کا بس نہ چلتا تھا کہ اگر جرمنی میں اس قدر چولہے ہوتے کہ
ہم سب کو ان میں جھونکا جا سکتا تو وہ ہمیں خاکستر ہی کر دیتے۔
ہم جہاں بھی گئے، ہماری خوراک ایک ہی رہی۔ وہ ڈیڑھ سو
گرام کی روٹی جس میں آدھا تو لکڑی کا بُرادا ہوتا تھا، یا پھر ایک خاص قسم کی
سبزی۔ کچھ جگہوں پر ہمیں پینے کو گرم پانی دیا جاتا اور کہیں کہیں وہ بھی نہ ملتا۔
خیر یہ بتانے سے حاصل؟ آپ خود اندازہ کریں کہ جنگ سے پہلے میرا وزن چھیاسی کلو
گرام تھا اور خزاں تک بمشکل پچاس بھی نہ ہو گا۔ ہڈّیوں پر تھوڑا سا پوستین اور ان
دونوں چیزوں کو اُٹھانے کی ہمت تھی لیکن اس سب کے ساتھ نہ صرف مشقت کرنا تھی بلکہ
اپنی زبان بھی بند رکھنا تھی۔ اور مشقت ایسی کہ جُتنے والے گھوڑے کے بس سے بھی
باہر ہو!
ستمبر کا مہینہ شروع ہوا تو اُنہوں نے روسی قیدیوں میں سے ایک سو چالیس کو ڈریسڈن ؔ سے قریب ایک کیمپ بی۔۱۴ میں بھیج دیا۔ ہم لوگ وہاں کل دو ہزار کے لگ بھگ تو ہوں گے اور یہاں پتھر کوٹنے کا کام تھا۔ ہر شخص پر یومیہ چار مکعب میٹر بجری توڑنے کی مشقت لازم تھی اور آپ سوچئے کس شخص پر لازم تھی، وہ جو بیچارہ جسم اور روح کے رشتے کو بصد مشکل قائم رکھے تھا۔ اور پھر جب یہ مشقت شروع ہوئی تو دو مہینوں کے اندر اندر ہمارے ایک سو بیالیس کے گروہ سے صرف ستاون لوگ زندہ بچے! کیسا لگا دوست؟ مشکل؟
ہمارے پاس تو اپنے ساتھیوں کی تدفین کا وقت بھی نہیں ہوتا تھا۔ پھر اس پہ طرہّ کہ کیمپ میں افواہ پھیلی کہ جرمنوں نے اسٹالن ؔ گراڈ پر قبضہ کرلیا ہے اور اب سائبیریاؔ کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں۔ یہ مَرے پہ سَو دُرّے کے مصداق تھا۔ وہ ہمیں آنکھ اُٹھا کر نہ دیکھنے دیتے گویا ہمیں جرمنی کی مٹی میں پیوند ہونا تھا۔
ایک شام جب ہم کام سے واپس اپنی جھونپڑی میں لوٹے۔ اس روز دن بھر بارش رہی تھی اور ہمارے تن کے چیتھڑے پانی میں شرابور تھے۔ ہم سرد ہوا میں اتنے ٹھٹھر رہے تھے کہ ہم دانتوں کو بجنے سے روک نہ پا ئے۔ خُشک یا گرم ہونے کا کوئی انتظام نہ تھا اور اس پہ بھوک کا یہ عالم کہ الحزر! لیکن ہمیں شام کو کھانا نہیں ملا کرتا تھا۔
میں نے اپنے بھیگے کپڑے
اُتار کر پھینکے اور کہا،
’’وہ ہمیں ایک دن میں چار مکعب میٹر پہ مشقت کرنے کا
کہتے ہیں لیکن ایک مکعب میٹر کی قبر میں ہم خود بآسانی سما سکتے ہیں !‘‘
بس اتنا ہی میں نے کہا تھا اور آپ یقین کریں کہ خود میرے ساتھیوں میں سے ایک غلیظ کُتا، کیمپ کمانڈنٹ کے پاس چلا گیا اور میری تلخ نوائی کی چغلی کھا ڈالی! کیمپ کمانڈنٹ، جسے ’لیگر فیوہرر‘ بھی کہتے تھے، مُلرؔ نام کا ایک جرمن تھا۔ ذیادہ لمبے قد کا نہ تھا، موٹا اور بال ایسے جیسے دھاگوں کا گچھا جو تمام بلیچ کئے گئے تھے، سر کے بال، پپوٹے اور حتیٰ کہ اسکی آنکھیں بھی بے رنگ تھیں، البتہ یہ اُبلی ہوئی آنکھیں تھیں۔ وہ آپ کی، میری طرح روسی زبان بولتا تھا، بلکہ کسی حد تک والگاؔ کے لب و لہجے میں بولتا تھا جیسے وہ وہیں کا پلا بڑھا ہو۔ اور وہ جو گالیاں بکتا تھا! الامان! مجھے حیرت ہوتی تھی کہ اس حرامزادے نے یہ ’ہُنر‘ کہاں سے سیکھا تھا۔ وہ ہمیں بلاک (ہمارے جھونپڑوں کو وہ ’بلاک‘ کہتے تھے) کے سامنے قطار میں کھڑا کرکے معائنے کیلئے آتا تھا تو ہماری قطار کے گرد ایس ایس کے سپاہی کھڑے ہوتے اور وہ اپنا دایاں ہاتھ اپنے پیچھے باندھ کر قطار کے سامنے چلتا تھا۔ وہ چمڑے کے دستانے پہنتا تھاجن کے اندر کی جانب سیسے کی تہہ انگلیوں کو بچانے کے لئے جَڑی تھی۔ وہ ہماری قطاروں میں آتا اور گھونسے مار کر قیدیوں کی ناک لہو لہان کر دیتا۔ وہ اسے نزلے زکام سے بچائے رکھنے کی دوا کہتا تھا۔ کیمپ میں چار بلاک تھے اور وہ باری باری چاروں بلاکوں میں ’’دوا‘‘ دینے آتا تھا اور یکے بعد دیگرے تمام بلاکوں میں مختلف دنوں میں آتا تھا۔ وہ حرامزادہ باقاعدگی سے آتا تھا اور اُس نے کبھی چھٹی نہیں کی۔ ایک بات جو وہ کبھی نہیں سمجھ سکا، احمق، وہ یہ تھی کہ وہ معائنہ شروع ہونے سے پہلے سامنے آ کھڑا ہوتا تھا اور گالیاں بکنا شروع کردیتا تھا۔ وہ وہاں کھڑا ہو کر جس حد تک ہو سکتا، ہمیں روسی زبان میں بُرا بھلا کہتا تھا اور آپ کو پتہ ہے، یہ ہمیں بھلا لگتا تھا۔ دیکھیں، یہ لفظ اپنے اپنے سے لگتے تھے گویا اپنے وطن کی جانب سے ہوا چل رہی ہو۔اگر اُسے یہ پتہ ہوتا کہ اُس کی یہ گالم گلوچ ہمیں یک گونہ تسکین دیتی تھی تو وہ ہمیں روسی زبان میں گالیاں ہرگز نہ بکتا اور اپنی ہی زبان میں لگا رہتا۔ ہمارا ماسکوؔ کا ایک ساتھی اکثر اُس سے اُلجھ پڑتا تھا کیونکہ اُس کا کہنا تھا کہ ’’جب وہ اس روسی زبان میں واہی تباہی بکتا ہے تو میں آنکھیں بند کر کے یوں محسوس کرتا ہوں جیسے میں ماسکوؔ میں کسی جگہ پر ہوں اور مجھے یوں غنودگی سی طاری ہونے لگتی ہے جیسے میں نے بیئر کا گلاس پی رکھا ہے‘‘
خیر جس شام میں نے وہ
ایک مکعب میٹر والی بات کی تھی، کمانڈنٹ کی جناب میں میری پیشی ہوئی۔ سرِ شام ایک
مترجم اور دو سنتری ہمارے جھونپڑے کی طرف آئے،
’’سوکولیفؔ، آندرے؟‘‘
اُنہوں نے پوچھا تو میں نے بتایا کہ میں ہی ہوں۔
’’باہر نکلو، جلدی چلو، کمانڈنٹ صاحب تم سے ملنا چاہتے
ہیں‘‘
مجھے اندازہ ہو گیا کہ
وہ مجھ سے کیوں ملنا چاہتا تھا۔ میں اپنے تمام ساتھیوں سے الوداع ہوا کیونکہ ان سب
کو اندازہ تھا کہ اب شائد میں زندہ رہنے والا نہ تھا۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور
سنتریوں کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ جب میں کیمپ کے احاطے سے گزر رہا تھا تو میں نے
نگاہیں اُٹھا کر ستاروں کو دیکھا اور انہیں الوداع کہا، پھر دل میں کہا،
’’اچھا تو آندرے سوکولیفؔ قیدی نمبر ۳۳۱، تمہارے لئے شدید ترین
اذیت کی سزا ہے‘‘
مجھے ارینہؔ اور بچوں
کے خیال نے غمزدہ تو کیا لیکن میں نے اس پر قابو پایا اور خود کو کمانڈنٹ کے پستول
کا سامنا کرنے کے لئے تیار کیا کہ جیسا کہ ایک فوجی کو کرنا چاہیئے تاکہ دُشمن کو
پتہ نہ چل سکے کہ زندگی سے بچھڑتے ہوئے آخری لمحہ میرے لئے کتنا کڑا تھا، اگر
واقعی بہت بُرا ہونے والا تھا!
کمانڈنٹ کے کمرے میں کھڑکیوں پر پھول آراستہ کئے گئے
تھے۔ یہ ہمارے فوجی کلبوں کی طرح ایک صاف ستھری جگہ تھی۔ کمانڈنٹ کی میز کے گرد
کیمپ کے تمام افسران بیٹھے تھے۔ ان میں پانچ افسران بیٹھے گوشت کھا رہے تھے اور
پینے میں لگے تھے۔ میز پر ایک بڑی بوتل کھلی پڑی تھی، کافی ساری روٹیاں، گوشت اور
چربی، سیب کا مربہ اور ہر طرح کے ٹین کے ڈبے کھلے پڑے تھے۔ میں نے ان سب ’فضولیات‘
پر ایک نظر ڈالی اور آپ یقین نہیں کریں گے کہ مجھے اتنا بُرا محسوس ہوا کہ مجھے
قَے آتے آتے رہ گئی۔ دیکھئے، میں ایک بھیڑئیے کی مانند بھوکا تھا اور مجھے تو
بھول ہی گیا تھا کہ انسانوں کے کھانے کس طرح کے ہوتے ہیں اور اب یہ صورت حال تھی
کہ یہ کس کچھ میرے سامنے پڑا تھا۔ میں نے کسی طرح اپنے احساسات پر قابو پا لیا
لیکن میز سے نظریں ہٹانا میرے لئے ازحد مشکل تھا۔
میرے عین سامنے مُلرؔ
بیٹھا تھا، کافی حد تک نشے میں دُھت، اپنے پستول سے کھیلتے ہوئے ایک ہاتھ سے دوسرے
ہاتھ میں اچھال رہا تھا۔ اُس نے کسی سانپ کی طرح اپنی نظریں مجھ پر جما رکھی تھیں۔
خیر، میں ’ہوشیار‘ حالت میں کھڑا ہو ا، اپنی ٹوٹی پھوٹی ایڑیاں جوڑ کر بآوازِ
بلند کہا،
’’جناب! جنگی قیدی آندرے سوکولیفؔ آپ کی خدمت میں حاضر
ہے!‘‘
’’تو تُم روسی! چار مکعب میٹر بجری توڑنے
کی مشقت تمہارے لئے کافی ہے! ہے ناں؟؟‘‘
اُس نے مجھ سے کہا۔
’’جی ہاں کمانڈنٹ صاحب!‘‘
میں نے جواب دیا۔
’’اور کیا ایک مکعب میٹر تمہاری قبر کیلئے کافی جگہ ہے؟‘‘
’’جی ہاں محترم کمانڈنٹ! کافی ہے، بلکہ اضافی ہے!‘‘
میں نے کہا تو وہ اُٹھ کھڑا ہوا۔
’’میں اس پر تمہیں عزت و تکریم دیتا ہوں،
یعنی یہ کہ ان الفاظ پر میں تُمہیں اپنے ہاتھ سے گولی ماروں گا!! یہاں تو گڑ بڑ ہو
جائے گی۔۔۔ میں تمہیں صحن میں لے جاؤں گا جہاں تمہاری رُخصتی ہو گی۔۔۔‘‘
اُس نے کہا۔
’’جیسے آپ بہتر سمجھیں‘‘
میں نے کہا۔
وہ ایک لحظے کو کھڑا کچھ سوچتا رہا پھر اُس نے پستول میز
پر اچھال دیا اور بوتل سے شراب گلاس میں اُنڈیلی، روٹی کا ایک بڑا ٹکڑا توڑا اور
مجھے دیتے ہوئے بولا،
’’روسی جوان! مرنے سے پہلے ذرا جرمن فوج کی فتح کا جام
تجویز کر لو!‘‘
میں، کہ شراب کا گلاس اور روٹی کی ٹکڑا اس کے ہاتھ سے لے
چکا تھا، جب میں اس کے یہ الفاظ سُنے تو مجھے کسی چیز نے اندر سے ٹہوکا دیا،
’’میں؟ ایک روسی فوجی، اپنے دُشمن کی فتح کا جام تجویز
کروں گا؟ تُم اور کیا کر لو گے کمانڈنٹ صاحب، میرے لئے یہ بھی بہت ہو گا۔ تُم اپنی
شراب سمیت جہنم میں جاؤ‘‘
میں نے سوچا۔میں نے گلاس واپس میز پر رکھا اور روٹی بھی۔
’’آپ کی میزبانی کا شکریہ جناب، میں شراب نہیں پیتا‘‘
میں نے کہا تو وہ مسکرا دیا۔
’’اچھا ہماری فتح کا جام نہیں پیو گے تو اپنی موت کا جام
ہی تجویزکرو پھر ‘‘
وہ بولا۔ اب اور کیا کھونے کو باقی تھا۔
’’میری موت کیلئے! اور اس کے بعد دکھوں سے نجات کیلئے!‘‘
میں نے کہا اور ساتھ وہ گلاس دو گھونٹ میں غٹا غٹ پی
گیا۔ لیکن میں نے روٹی کو ہاتھ تک نہ لگایا۔ میں نے اپنے ہاتھ سے اپنے ہونٹ پونچھے
اور کہا،
’’آ پ کی میزبانی کا شکریہ جناب، اب میں رُخصتی کیلئے
تیار ہوں کمانڈنٹ صاحب!‘‘
لیکن وہ تیز نظروں سے مجھے دیکھے جا رہا تھا۔
’’مرنے سے پہلے لقمہ بھر کھا بھی لو!‘‘
اُس نے کہا تو میرا جواب تھا؛
’’میں پہلے جام کے بعد کبھی کچھ نہیں کھاتا!‘‘
اُس نے دوسرا جام بھر ا اور مجھے تھما دیا۔ میں نے دوسرا
گلاس بھی پی لیا لیکن روٹی کو چھوا تک نہیں۔ میں نے سب کچھ داؤ پہ لگانے کی ہمت
کی۔
’’بہرحال مرنے سےپہلے میں مخمور ہوں گا‘‘
میں نے سوچا۔ کمانڈنٹ کی بھنویں تن گئیں۔
’’رُوسی! شرماؤ مت! کچھ کھاتے کیوں نہیں؟‘‘
کمانڈنٹ بولا لیکن میں اپنی ضد پر تھا۔
’’معاف کیجئے گا محترم کمانڈنٹ! میں دوسرے جام کے بعد
بھی کچھ نہیں کھاتا!‘‘
میں نے کہا تو وہ اپنے گال پُھلا کر زور سے ہنسا اور ساتھ کچھ جرمن میں کہا، شاید میرے الفاظ کا جرمن ترجمہ اپنے ساتھیوں کوبتا رہا تھا۔ وہ سب بھی ہنس دئیے اور اپنی نشستوں پہ مُڑ کے میری طرف متوجہ ہوئے تو میں نے ان کی نگاہوں میں نرمی کا کوئی شائبہ محسوس کیا۔ کمانڈنٹ نے میرے لئے تیسرا گلاس بھرا اور اس کا ہاتھ ہنسی کے مارے اب بھی تھرتھرا رہا تھا۔ میں نے یہ گلاس آہستگی سے پیا، روٹی سے تھوڑا ٹکڑا کھایا اور باقی میز پر رکھ دیا۔ میں ان حرامیوں کو دکھانا چاہتا تھا کہ میں بھوک سے ادھ موا ہونے کے باوجود بھی اُن کے پھینکے گئے ٹکڑوں کو اُن کی منشأ کے مطابق جانوروں کی طرح نہیں کھانے والا تھا کیونکہ یہ میری روسی خودداری اور عزتِ نفس کا سوال تھا۔
اس کے بعد کمانڈنٹ نے
اپنے چہرے پر ایک سنجیدگی طاری کی، اپنی چھاتی کے تمغے درست کئے اور غیر مسلح، میز
کے پیچھے سے نکل آیا۔
’’دیکھو سوکولیفؔ، تُم ایک حقیقی روسی فوجی ہو! تُم ایک
عمدہ فوجی ہو! میں بھی ایک فوجی ہوں اور قابل دُشمن کی قدر کرتا ہوں۔ میں تمہیں
نہیں ماروں گا۔ اس کے علاوہ یہ کہ آج ہماری بہادر افواج والگاؔ تک پہنچ کر
اسٹالنؔ گراڈ پر کُلّی طور پر قابض ہو چکی ہیں۔ یہ ہمارے لئے خوشی کا موقع ہے اور
اسی خوشی میں تمہیں زندگی عطا کی جاتی ہے۔ اپنے بلاک واپس جاؤ اور یہ اپنی بہادری
کے صلے میں اپنے ساتھ لے جاؤ!‘‘
اُس نے میز سے روٹی کا ٹکڑا اور گوشت کی ایک چانپ اُٹھا کر مجھے دیتے ہوئے کہا۔
میں نے جلدی سے روٹی کا ٹکڑا بھینچ کر سینے سے لگایا، دوسرے ہاتھ میں گوشت کی چانپ پکڑی۔ میں اس ردِ عمل پر اتنا حیران تھا کہ مجھے کمانڈنٹ کا شکریہ تک ادا کرنے کا دماغ نہ رہا۔ میں بائیں گھوم کر پیچھے مُڑا اور دروازے کی طرف چلا۔ اس دوران مجھے یہ خیال آ رہا تھا کہ اب کسی لمحے پیچھے سے گولی سر ہو گی اور میرے شانوں کو چیر ڈالے گی اور میں یہ چیزیں کبھی اپنے ساتھیوں تک نہ لے جاسکوں گا۔ لیکن کچھ نہ ہوا۔ موت ایک بار پھر میرے قریب سے گزر گئی تھی اور میں نے صرف اسکی سرد سانس کی خنکی محسوس کی تھی۔
میں لڑکھڑائے بغیر کمانڈنٹ کے کمرے سے نکلا اور روانی میں چلتا گیا۔ اپنے جھونپڑے میں آ کر میں دھڑام سے سیمنٹ کے فرش پر گر ا اور بے ہوش ہو گیا۔ لڑکوں نے اگلی صبح مجھے جگایا تو ابھی اندھیرا تھا۔
’’بتاؤ ناں! کیا ہوا تھا؟‘‘
سب پوچھنے لگے۔ میں نے کمانڈنٹ کے دفتر والی بپتا یاد کر
کے اُنہیں سُنا ڈالی۔
’’اچھا وہ کھانا کس طرح تقسیم کرو گے؟‘‘
میرے ساتھ والے نے کانپتی آواز میں پوچھا۔
’’ سب کو برابر حصہ!‘‘
میں نے اُسے بتایا۔ ہم نے روشنی کے بڑھنے کا انتظار کیا، جب روشنی ہوئی تو ہم نے روٹی اور گوشت کو ایک پتلے تار سے کاٹا۔ ہم میں سے ہر ایک کو ماچس کی ڈبیا جتنا روٹی کا ایک ایک ٹُکڑا ملا اور ایک ذرّہ بھی ضائع نہ ہونے دیا گیا۔ اور چربی والا گوشت تو بس اتنا مل سکا کہ ہم اپنے ہونٹ ہی چکنے کر سکے، تاہم ہم نے برابر تقسیم کی۔
جلد ہی ہم میں سے تین
سو نسبتاً توانا لوگوں کو ایک دلدل کی نکاسی پہ لگا دیا گیا اور اس کے بعد ہم
روہرؔ کی کوئلے کی کانوں میں بھیج دئیے گئے۔ یہاں میں سن چوالیس تک رہا۔ اس وقت تک
ہماری فوج نے جرمنی کے اتنے کس بل نکال دئیے تھے کہ نازیوں نے ہم قیدیوں کو حقارت
کی نظر سے دیکھنا کم کر دیا تھا۔ ایک دن اُنہوں نے ہم تمام، دن والے مزدوروں کو
قطار میں کھڑا کیا اور ایک معائنہ کار لیفٹیننٹ نے مترجم کی مدد سے پوچھا،
’’تُم میں سے کوئی شخص فوج میں یا جنگ سے پہلے ڈرائیور رہا
ہے؟ کوئی ہے تو ایک قدم آگے نکل آئے!‘‘
ہم میں سے تقریباً سات
لوگ جو پہلے ڈرائیور رہ چکے تھے، باہر نکل آئے۔ اُنہوں نے ہمیں کچھ پرانی
ڈانگریاں دیں اور سنتریوں کی نگرانی میں ہمیں پوسٹڈمؔ لے گئے۔ یہاں ہم سب بکھر
گئے۔ مجھے ٹوٹؔ کے ساتھ منسلک کر دیا گیا۔ یہ ادارہ جرمنوں کے بقول سڑکیں اور
دفاعی اقدامات کی تعمیر کرتا تھا۔
میں جرمن آرمی کی کور آف انجنیئرز کے ایک میجر کی
اوپلؔ ایڈمرل کار کا ڈرائیور تعینات ہوا۔ اور یہ ایک اصلی نازی خنزیر تھا۔ میانہ
قد، مٹکے جیسا پیٹ، جتنا لمبا، اُتنا ہی چوڑا اور پیٹھ اتنی بڑی جیسے کسی کسبی کی
ہوتی ہے۔ اُس کی ٹھوڑ کوئی تین تہوں میں اُس کے گریبان پر لٹک رہی ہوتی تھی اور
اسی طرح اس کی گردن میں بھی آگے پیچھے سے تین موٹے موٹے حلقے تھے۔ کوئی ایک سو
کلو خالص چربی تو وہ اُٹھائے پھرتا ہو گا۔ جب وہ چلتا تھا تو ریل کے انجن کی طرح
پھنکارتا تھا اور کھانے بیٹھتا تھا تو جم جاتا تھا۔ وہ دن بھر برانڈی کی بوتل سے
چسکیاں لیتا اور گھونٹ بھرتا رہتا۔ وہ سڑک پہ رُک جاتا تھا، پنیر میں سے کچھ کاٹ
کر کھاتا، کچھ پیتا اور کبھی خوشگوار موڈ میں ہوتا تو بچا کھچا ٹکڑا میری طرف بھی
کسی کُتے کی مانند اُچھال دیتا تھا۔وہ کبھی میرے ہاتھ میں نہیں تھماتا تھا۔اور یہ
تو وہ اپنی شان کے شایان ہی نہیں سمجھتا تھا۔ لیکن پھر بھی ان حالات کا قیدی کیمپ
سے کوئی موازنہ نہ تھا اور کم سے کم میں نے ایک انسان نظر آنا شروع کر دیا تھا۔
حتیٰ کہ اب میرا وزن بھی بڑھنے لگا تھا۔
لگ بھگ دو ہفتوں تک میں میجر موصوف کو لے کر پوسٹڈمؔ اور برلنؔ کے درمیان سفر کرتا رہا اور پھر اُسے سگلے محاذ پر ہماری سپاہ کے خلاف تعمیرات کیلئے بھیج دیا گیا۔ اور پھر میری نیندیں بھی حرام ہو گئیں۔ اب ہمہ وقت یہی خیال ذہن میں رہتا کہ کس طرح یہاں سے فرار ہو کر اپنی سپاہ تک پہنچ جاؤں، اپنے مُلک۔۔۔
ہم پولوٹسکؔ کے قصبے میں پہنچے۔ صبح کے وقت آج دو سال بعد میں نے روسی توپخانے کی گھن گرج سُنی اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے میرے دل کی دھڑکن کو کیا ہونے لگا یہ سُن کر۔۔۔ حتیٰ کہ ارینہؔ سے نئی نئی دل لگی کے دنوں میں بھی دل اس طرح نہیں دھڑکتا تھا جیسے آج دھڑکا۔ یہاں سے اٹھارہ کلومیٹر دور مشرق میں لڑائی جاری تھی۔ قصبے پر قابض جرمن حد درجہ بے چین اور بے سکون تھے اور میرے صاحب نے تو بہت ذیادہ پینی شروع کردی تھی۔ ہم دن بھر گھومتے پھرتے اور وہ قلعہ بند ی اور دفاع تعمیر کرنے کے حوالے سے ہدایات دیتا رہتا اور رات کو اکیلا بیٹھ کر پیتا تھا۔ وہ بہت سُوج جاتا تھا اور اسکی آنکھوں کے نیچے سُرخ تھیلے سے لٹکنا شروع ہو جاتے تھے۔
خیر میں نے سوچا کہ اب ذیادہ انتظار نہیں ہو سکتا، اب موقع ہے فرار ہونے کا اور میں اکیلا بھی فرار نہیں ہوں گا، میں اس پیٹُو میجر کو بھی ساتھ لے جاؤں گا جو میرے کام آئے گا۔
کاٹھ کباڑ کے ایک ڈھیر پر مجھے ایک آہنی سلاخ ملی جسے میں نے کپڑے میں لپیٹ لیا تاکہ میں اس سے کوئی ضرب لگاؤں تو وہ خونچکاں نہ ہو۔ پھر میں نے ٹیلی فون کی تار کا ایک ٹکڑ ا لیا اور جو کچھ مجھے مزید درکار تھا، سامنے کی سیٹ کے نیچے چھپا لیا۔ فرار سے دو دن پہلے ایک شام کو جب میں ایندھن بھروا رہا تھا تو میں نے شراب کے نشے میں دھت ایک جرمن سپاہی کو لڑکھڑاتے ہوئے، دیواروں سے ٹکراتے دیکھا تو میں نے اسے ساتھ لیا، ایک تباہ شدہ عمارت میں لے جا کر اسکی وردی اور ٹوپی اُتاری اور اپنے قبضے میں لے لی۔ اب میں تیار تھا!
۲۹ جون کی صبح مجھے میجر نے حُکم دیا کہ اُسے ٹروسنِٹسا ؔ کی جانب لے جاؤں۔ وہ وہاں پر کسی دفاعی تعمیر کے کام کا انچارج تھا۔ ہم روانہ ہو گئے۔میجر پچھلی سیٹ پر دُھت بیٹھا تھا اور اگلی سیٹ پر میری یہ حالت کہ دل اُچھل کر حلق سے باہر آرہا تھا۔ میں نے گاڑی کافی تیز چلائی لیکن قصبے سے باہر پہنچ کر رفتار دھیمی کر لی اور پھر روک ہی دی۔ میں نے اُتر کر ادھر اُدھر دیکھا تو کافی پیچھے دو لاریاں آہستہ آہستہ آرہی تھیں۔ میں فولادی سلاخ نکالی اور دروازہ کھول کر دیکھا کہ میجر پچھلی سیٹ پر پڑا یو ں خراٹے لے رہا تھا جیسے بیوی کے پہلو میں سویا پڑا ہو۔ میں نے اس کی کنپٹی پر ایک زوردار ضرب لگائی، اس کا سر ڈھلک گیا۔ پھر دوسری ضرب اپنی یقین دہانی کیلئے لگائی لیکن میں اسے جان سے نہیں مارنا چاہتا تھا بلکہ اسے زندہ لے جانا چاہ رہا تھا۔ اُس کے پاس ہماری فوج کو بتانے کیلئے کافی کچھ تھا۔ میں نے اس کے پہلو سے پستول الگ کیا اور اپنی جیب میں ڈال لیا۔ میجر کو ٹیلی فون کے تار سے اس طرح باندھ دیا کہ تیز گاڑی چلانے میں وہ دائیں بائیں لڑھک نہ جائے۔ میں نے جرمن وردی اور ٹوپی پہنی اور اس جانب گاڑی دوڑا دی جدھر زمین لرز رہی تھی، جہاں لڑائی ہو رہی تھی۔
میں جرمن صفوں میں دو بڑے مورچوں کے درمیان سے گاڑی چلاتا ہوا گزرا تو چند مشین گن بردار فوجی سامنے سے نمودار ہوئے۔ میں نے دانستہ گاڑی کی رفتار کم کر لی تاکہ وہ دیکھ سکیں کہ میرے ساتھ ایک میجر بیٹھا تھا۔ وہ رائفلیں لہرا کر مجھے آگے جانے سے منع کر رہے تھے لیکن میں ظاہر کیا کہ کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی اور تقریباً ۸۰ کی رفتار سے آگے نکل گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتے اور گولی چلاتے، میں گولہ باری سے پڑنے والے گڑھوں کے درمیان سے ہو کر ’نو مین لینڈ‘ تک پہنچ چکا تھا۔ عقب سے جرمنوں نے فائرنگ کی اور سامنے سے ہمارے اپنے لڑکے غضبناک ہو کر فائرنگ کرنے لگے۔ گولیوں نے گاڑی کی ونڈ اسکرین اور ریڈی ایٹر کو چھید دیا، پاس ہی ایک جھیل کنارے درختوں کا ایک جھنڈ تھا۔ میں اپنے سپاہیوں کو گاڑی کی طرف بڑھتے دیکھ کر گاڑی اُس جھُنڈ میں لے گیا اور گاڑی روک کر اس سے باہر نکل آیا۔ میں زمین پر گر گیا اور مٹی کو چومنے لگا۔ مجھ سے سانس بھی نہیں لیا جا رہا تھا۔
ایک نو عمر لڑکا جس کے
شانوں پر خاکی پٹیاں تھیں، پہلے میرے قریب پہنچا اور مجھے دیکھ کر زہر خند ہنسی
ہنسا،
’’ آہا!! غلیظ جرمن! راستہ بھول گئے ناں؟‘‘
میں نے اپنا جرمن کوٹ
نوچ کر الگ کیا، جرمن ٹوپی اپنے قدموں پر پھینکی اور اُس سے گویا ہوا۔
’’ پیارے بچے! مَیں ورونزہؔ میں پیدا ہونے والا جرمن
ہوں! دیکھو برخوردار، میں جنگی قیدی تھا! چلو اب اس موٹے خنزیر کو کھول کے گاڑی سے
نکالو! یہ بریف کیس لو اور اسے اپنے کمانڈر تک پہنچاؤ!‘‘
میں نے اپنا پستول بھی اس کے حوالے کر دیا اور پھر مجھے بھی ایک سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے افسر کے حوالے کرتے کرتے شام تک ڈویژن کے کمانڈر، ایک کرنل صاحب تک پہنچا دیا گیا۔(عام طور پر ایک فُل کرنل ایک رجمنٹ یا بریگیڈ کی کمان کرتا ہے اور ڈویژن کی کمان، جو کہ بریگیڈ سے بڑی اکائی ہے، میجر جنرل کرتا ہے لیکن عالمی جنگوں کے دوران سینئیر، تجربہ کار افسران کی شدید کمی کے باعث ہر فوج میں بڑی فارمیشنیں ایک عہدے کم کے افسران کو بھی کمان کرنا پڑیں: مترجم) تب تک مجھے کھانا کھلایا گیا اور نہلا دُھلا کر ایک نئی وردی دی گئی۔ میں جب کرنل کے مورچے میں گیا تو میں ظاہر و باطن میں بہت صاف ستھرا اور ہلکا پھلکا محسوس کررہا تھا اور میں نے باقاعدہ ضابطے کے مطابق نئی وردی پہن رکھی تھی۔ کرنل اپنی میز سے اُٹھا اور میرے قریب آ کر اُس نے تمام افسران کی موجودگی میں میں میرا بوسہ لیا اور کہا،
’’شکریہ سپاہی! اس تحفے کا شکریہ جو تُم ہمارے لئے لے آئے ہو! تمہارا یہ میجر اور بریف کیس ہمیں اتنی معلومات فراہم کر سکتا ہے جتنی شاید ہمیں بیس جرمن سپاہیوں کے پکڑے جانے سے نہ مل سکتیں۔ میں تمہارے لئے تمغے کی سفارش کروں گا‘‘ اُس کے الفاظ اور مشفقانہ لہجے سے میں بہت متاثر ہوا۔ میرے ہونٹ لرز رہے تھے اور میں بمشکل ہی کہہ سکا،
’’کامریڈ کرنل! آپ میرا تبادل ہکسی
پیادہ یونٹ میں کروا دیں‘‘
کرنل ہنسا اور اس نے میرے کاندھے پر دَھول جمائی،
’’اپنی ٹانگوں پہ تو بمشکل کھڑے ہو سکتے ہو تُم، لڑو گے کیا! میں تمہیں ہسپتال بھیج رہا ہوں جہاں وہ پہلے تمہیں کچھ خوراک دیں گے، کچھ تمہاری صحت بہتر کریں گے۔ اس کے بعد تُم ایک مہینے کی چھٹی پہ گھر جاؤ گے اور تمہاری واپسی پہ ہم فیصلہ کریں گے کہ تمہارا کیا کیا جائے!‘‘
کرنل اور اس کے ساتھ کے تمام افسروں نے مجھ سے ہاتھ ملایا اور مجھے الوداع کہا۔ باہر جاتے ہوئے میرا سر چکرا رہا تھا کہ گذشتہ دو سال میں مَیں بھول ہی گیا تھا کہ میرے ساتھ کبھی کوئی انسانی سلوک بھی ہوا ہو۔ یقین کیجئے میرے دوست، کہ مجھے افسروں سے بات کرتے ہوئے ایک خوف سے، کہ گویا مجھ پر تشدد کیا جائے گا، سر جھکا کر بات کرنے کی عادت ختم کرنے میں کافی وقت لگا۔ نازی کیمپوں میں ہمیں یہی تربیت دی گئی تھی۔
میں جونہی ہسپتال پہنچا، میں نے ارینہؔ کو خط لکھا۔ میں نے اسے مختصر الفاظ میں بتایا کہ میں کس طرح جنگی قیدی ہوا اور کس طرح ایک جرمن میجر کو ہمراہ لے کر بھاگ نکلا۔ نجانے کس چیز نے مجھے ایک بچے کی طرح شیخی بگھارنے پر مجبور کی، مجھ سے یہ کے بغیر بھی نہ رہا گیا کہ کرنیل کے مجھے تمغہ دلوانے کا وعدہ کر رکھا تھا۔ لگ بھگ دو ہفتے تک میں بس سوتا تھا اور کھانا کھاتا تھا۔ وہ ایک وقت میں مجھے تھوڑا تھوڑا کھانا کھلاتے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اگر مجھے ایک بار ہی اتنا کھانا کھلا دیا جائے، جتنا میں چاہتا ہوں، تو یہ میرے لئے مُضر ہو گا۔ لیکن دو ہفتے گزرنے کے بعد میرا کھانا کھانے کو بھی جی نہیں چاہتا تھا۔ ابھی تک گھر سے خط کا جواب نہیں آیا تھا اور مجھے بُرے بُرے وہم اور خیالات آرہے تھے اور کچھ کھایا جا رہا تھا، نہ سویا جا رہا تھا۔ پھر تیسرے ہفتے میں ایک خط ورونزہؔ سے آیا لیکن یہ ارینہؔ کی طرف سے نہ تھا، یہ ہمارے ہمسائے کی طرف سے تھا۔ خُدا نہ کرے ایسا خط کبھی کسی کی طرف آئے! اُس نے لکھا تھا کہ جرمنوں نے طیارہ ساز فیکٹری پر بمباری کی تھی اور میرے گھر پر براہِ راست ایک بم آن گرا تھا۔ جب بم گرا تھا تو ارینہؔ اور بیٹیاں گھر پر ہی تھیں۔ اُس نے لکھا تھا کہ کچھ نہیں بچا ماسوائے گھر کی جگہ ایک بڑے سے گڑھے کے! پہلی بار تو میں اس خط کو پورا نہ پڑھ سکا۔ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور میرا دل اس طرح بھنچ گیا جیسے سکڑ کر ایک چھوٹی سی گیند بن گیا ہو۔۔۔ جو شاید اس شکنجے سے کبھی نکل نہ پائے۔ میں واپس اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ جب میری قوت کچھ بحال ہوئی تو میں نے سارا خط پڑھ لیا۔ میرے ہمسائے نے لکھا تھا کہ بمباری کے وقت اناطولیؔ شہر گیا ہوا تھا۔ وہ شام کو واپس لوٹا تو اپنے گھر کی جگہ پڑنے والے گڑھے پہ ایک نگاہ ڈال کر واپس لوٹ گیا۔ جانے سے پہلے اُ س نے یہی بتایا کہ وہ محاذ پر جا رہا ہے!
جب میرا دل سنبھلا تو میں نے اپنے کانوں میں خون کی گردش کو سُنا۔ مجھے یاد آیا کہ کس طرح ریلوے اسٹیشن پر روانگی کے وقت ارینہؔ مجھ سے لپٹ گئی تھی۔ اُس عورت کا دل یقیناً جانتا تھا کہ ہم اس دُنیا میں پھر کبھی نہیں ملیں گے۔ لیکن میں نے اُس کو دھکا دے دیا تھا۔ کبھی میرا گھر بھی ہوا کرتا تھا، اپنا خاندان اور اس سب کے بننے میں کئی سال لگے تھے لیکن ایک ہی جھماکے میں سب کچھ ختم ہو گیا اور میں اکیلا رہ گیا۔
’’یہ درہم برہم زندگی۔۔۔ کاش یہ کوئی خواب ہو!‘‘
میں سوچنے لگا۔ میں جب قیدی تھا تو ہر رات خیالوں میں مَیں ارینہؔ سے باتیں کرتا تھا، بچوں سے باتیں کرتا تھا اور انہیں تسلیاں دیتا تھا اور وعدہ کرتا تھا کہ میں ایک دن گھر واپس ضرور آؤں گا لہٰذا اُنہیں رونا نہیں چاہیئے! ’میں سخت جان ہوں‘ ’میں یہ سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں‘ ’ہم سب ایک دن اکٹھے ہوں گے!‘ دو سال تک میں مَرے ہوؤں سے باتیں کرتا رہا تھا!!
وہ بھاری بھرکم آدمی ایک منٹ تک خاموش رہا۔ پھر بولا تو اُس کی آواز نیم جان سی تھی۔ ’’دوست! چلو سگریٹ پیتے ہیں! مجھے لگا جیسے میرادم گھُٹ جائے گا!‘‘
ہم نے سگریٹ جلایا۔ سیلاب ذدہ جنگل میں ہُد ہُد کے، پیڑوں پر چونچ ٹھونکنے کی آواز بلند محسوس ہو رہی تھی۔ گرم ہوا میں چناروں کے پتے کھڑکھڑا رہے تھے۔ بادل اونچے، ایستادہ بادبانوں کے پاس سے گزرتے نظر آرہے تھے لیکن خاموشی کے ان لمحوں میں بہار اور زندگی کی شادمانی سے بھرپور دُنیا قطعی مختلف لگ رہی تھی۔خاموش رہنا اتنا ہیجان انگیز تھا کہ مجھ سے پوچھے بنا رہا نہ گیا۔ میں نے سوال کیا، ’’پھر کیا ہوا؟؟‘‘
کہانی سُنانے والے نے جھجکتے ہوئے جواب دیا؛
پھر میں نے کرنیل سے ایک ماہ کی چھُٹی لی۔ ایک ہفتے بعد میں ورونزہ میں تھا۔ میں پیدل چل کر اس جگہ پر گیا جہاں میں کبھی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ وہاں گہرا سا ایک کھڈا تھا جو اب گندے پانی سے بھرا ہوا تھا۔ خود رو گھاس پھونس میری کمر تک آ رہا تھا۔ یہ جگہ اب بھی کسی قبرستان کے سے سکوت اور خالی پن کا احساس دے رہی تھی۔ کیا بتاؤں میرے دوست، میرے احساسات کتنے ابتر تھے! کچھ دیر تو میں غم کے عالم میں وہاں کھڑا رہا، پھر واپس اسٹیشن کی جانب چلا گیا۔ میں یہاں بمشکل ایک گھنٹا ٹھہرا ہوں گا۔ میں اسی روز واپس اپنے ڈویژن سے جا ملا۔
تقریباً ایک ماہ بعد مجھے خوشی کی ایک لہر سی نصیب ہوئی جیسے بادلوں کے درمیان کسی روزن سے سورج کی ایک کرن جھانکتی ہے۔ مجھے اناطولیؔ کے بارے میں خبر ملی! اُس نے کسی دوسرے محاذ سے مجھے خط لکھا تھا جس کے لئے میرا پتہ اُسے میرے اُسی ہمسائے سے ملا جس کا ذکر میں نے پہلے کیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ توپ خانے کے اسکول میں داخل ہوا تھا جہاں بالیقین اُس کی ریاضی کی قابلیت کام آئی۔ ایک سال بعد وہ اس ادارے سے امتیازی حیثیت میں فارغ التحصیل ہو کر محاذ پر چلا گیا۔ اب، اُس نے خط میں لکھا تھا کہ وہ کپتان کے عہدے پر ترقی پا چکا تھا اور ۴۵ سپاہیوں کی بیٹری کی کمان کر رہا تھا۔ اور یہ بھی کہ اب تک چھے تمغے بھی حاصل کر چکا تھا۔ مختصر الفاظ میں یہ کہ وہ اپنے باپ سے کہیں آگے نکل چکا تھا۔ مجھے ایک بار پھر اپنے بیٹے پر حقیقی فخر محسوس ہوا۔ کوئی کچھ کہے، میرا بیٹا اب کپتان تھا اور ایک بیٹری کی کمان کررہا تھا! یہ کچھ کم تو نہ تھا! اور پھر وہ چھے تمغے! اس سے اب کیا فرق پڑتا تھا کہ اُس کا باپ ہمہ وقت توپخانے کے گولے ڈھونے کی بیگار پہ لگا ہوا تھا! باپ تو اپنی عمر بِتا چکا تھا لیکن اُس کے سامنے، اُس کپتان کے سامنے آنے والی زندگی میں بہت کچھ تھا!
اب میں راتوں کو بوڑھے آدمیوں کے سے خواب آنکھوں میں سجا نے لگا کہ ایک دن جنگ ختم ہو جائے گی تو میں اپنے بیٹے کی شادی کروں گا اور پھر ہم مل کر رہیں گے! میں کچھ کام کاج کرلوں گا۔۔۔ بڑھئی والا کام! اور اپنے پوتوں کو سنبھالوں گا۔ ہر وہ کام جو بوڑھے لوگ کرتے ہیں۔ لیکن یہ بھی حسرتِ ناکام ہی ٹھہری! سردیوں میں ہماری پیش قدمی اتنی تیز تھی کہ ہمیں ایک دوسرے کو تواتر سے خط تک لکھنے کی فرصت نہ مل سکی۔ البتہ جنگ ختم ہونے سے قبل، برلنؔ کے قریب پہنچ کر میں نے ایک صبح اناطولیؔ کو خط لکھا اور دوسرے ہی روز اس کا جواب بھی آگیا۔ پتہ چلا کہ ہم دو مختلف راستوں سے پیش قدمی کر کے جرمن دارالحکومت تک پہنچے تھے اور اب بہت جلد ملنے والے تھے۔ اب مجھ سے اناطولیؔ کو ملنے کا مزید انتظار نہ ہو سکتا تھا اور پھر وہ لمحہ آ بھی گیا۔ نَو مئی کی صبح، یعنی جرمنوں پر ہماری فتح کے دن میرا اناطولیؔ کسی جرمن سنائپر کے ہاتھوں مارا گیا۔
شام کو کمپنی کمانڈر نے
مجھے بُلوا بھیجا۔ اُن کے دفتر میں ایک اجنبی سا کوئی توپ خانے کا افسر بیٹھا تھا۔
میں جونہی اندر گیا، وہ افسر یوں اُٹھ کھڑا ہوا جیسے کسی سینیئر سے مل رہا ہو۔
میرے کمانڈنگ افسر گویا ہوئے،
’’کرنل صاحب تمہیں ملنے آئے ہیں سوکولیفؔ!‘‘
اور پھر اُنہوں نے کھڑکی کی جانب رُخ پھیر لیا۔ مجھے ایک
جھرجھری سی آئی، مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ مجھ پر کوئی آفت آنے والی تھی۔ وہ
کرنل صاحب میرے قریب آئے اور بولے،
’’ایک باہمت باپ بنو! تمہارا بیٹا کیپٹن سوکولیفؔ آج
اپنی بیٹری میں مارا گیا ہے۔ میرے ساتھ چلو!‘‘
میں چکرا سا گیا لیکن میں اپنے قدموں پر قائم رہا۔ مجھے یہ اب بھی غیر حقیقی سا لگتا ہے کہ جس طرح وہ کرنل اور میں ایک بڑی سی کار میں سوار، ملبے سے اٹی سڑکوں اور گلیوں سے گزرے۔ مجھے اب دھندلا سا منظر یاد آتا ہے کہ سپاہیوں کی دو قطاریں ویلویٹ میں منڈھے تابوت کے گرد کھڑی تھیں۔ میرا اناطولیؔ اس طرح پُر سکون اور سپاٹ چہرے کے ساتھ تھا جیسے اس وقت آپ دکھائی دے رہے ہیں۔ ہاں! یہ میرا اناطولیؔ ہی تھا! لیکن یہ وہ نہیں بھی تھا! کیونکہ میرا بیٹا ایک بانکا سا جوان تھا جس کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ رہتی، اُچکے ہوئے کاندھوں والا، گردن کے نوکیلے سے کنٹھے والا جو اس کی پتلی گردن کے سامنے نمایاں ہوتا تھا لیکن یہاں تو ایک چوڑے شانوں والا، پورا پروان چڑھا ہوا مرد تھا، خوبصورت مرد۔ اُس کی آنکھیں ادھ کھُلی رہ گئی تھیں گویا وہ میرے آر پار کہیں دُور نظریں گاڑے ہو۔ وہ مسکراہٹ جو کبھی میرے بیٹے کے ہونٹوں پر ہوتی تھی، اب فقط اُس کے ہونٹوں کے کُنجِ لب پر مدھم سی باقی تھی۔ وہ اناطولیؔ جسے میں پہلے جانتا تھا، اُس کی مسکراہٹ۔ میں اُس کا بوسہ لیا اور ایک طرف ہو گیا۔ کرنل صاحب نی چند رسمی سی باتیں کیں۔ میرے اناطولیؔ کے دوست اپنے آنسو پونچھ رہے تھے لیکن میرے آنسو تو اندر ہی خشک ہو چکے تھے، میں رو نہ سکا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ آنسو جو تب ادا نہ ہو سکے، آج بھی مجھے اندر ہی اندر سے تکلیف دیتے ہیں۔
یوں میں نے اپنی آخری خوشی اس اجنبی، جرمن سرزمین میں دفنا دی۔ بیٹری کے سپاہیوں نے سلامی کی بندوقیں سَر کیں اور اپنے کمانڈر کو ابدی سفر پر رونہ کر دیا۔۔۔ اور میرے اندر کوئی چیز چھناکے سے ٹوٹ گئی۔ جب میں اپنے یونٹ پہنچا تو میں ایک بدلا ہوا انسان تھا۔ اس کے کچھ ہی عرصے بعد مجھے جنگی خدمات سے رخصت کر کے گھر بھیج دیا گیا۔ گھر؟ کہاں تھا گھر؟ ورونزہؔ؟ لیکن میں ورونزہؔ کس لئے جاتا؟ مجھے یاد تھا کہ میرے ایک دوست کو گذشتہ سرما میں بوجہ معذوری فوج سے نکال دیا گیا تھا جو کہ اب یوریاپنسکؔ میں رہتا تھا۔ اُس نے مجھے کہہ رکھا تھا کہ میں اُس کے پاس آکے رہوں، سو میں وہیں روانہ ہو گیا۔
میرے دوست اور اسکی بیوی کے ہاں اولاد نہ تھی۔ وہ گاؤں کے جوار میں ایک لکڑی کے گھر میں رہتے تھے۔ اُسے معذوری کی پنشن ملتی تھی لیکن وہ ایک لاری ڈپو میں ڈرائیور کے طور پر کام بھی کرتا تھا سو مجھے بھی وہاں کام مل گیا۔ میں اپنے دوست کے پاس مقیم ہو گیا اور انہوں نے مجھے گھر فراہم کیا۔ ہم گردونواح کا کافی سارا باربرداری کا کام کرتے تھے اور خزاں کے موسم میں ہم گیہوں کی نقل و حمل میں لگ جاتے۔ انہی دنوں میں اپنے اس نئے بیٹے سے متعارف ہوا جو اس وقت نیچے ریت پر کھیل رہا ہے۔
آپ اپنے معمول کے کام کاج سے واپسی پر پہلا کام جو کرتے ہیں، وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کیفے پہ جا کر کچھ کھائیں اور واڈکا کا ایک گلاس نوشِ جاں کریں کہ تھکن اُتر سکے۔ یہ بُری عادت ہے لیکن تب میرا پسندیدہ معمول تھا، مجھے تسلیم کرنا چاہیئے۔ خیر، ایک دن میں نے اس بچے کو کیفے کے قریب دیکھا اور اگلے روز پھر میری نظر اس پر پڑی۔ یہ ننھا سا، چیتھڑوں میں ملبوس بچہ تھا! اس کا چہرہ تربوز کے پانی اور گَرد کے آمیزے سے لتھڑا ہوا تھا، بہت ہی میلا اور بال بھی بکھرے ہوئے تھے لیکن اس آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو کہ بارش کے بعد آسمان پر نظر آنے والے تاروں میں ہوا کرتی ہے۔ مجھے اس بچے کا ایسا اشتیاق پیدا ہوا کہ میں اس کی غیر موجودگی کو محسوس کرنے لگا تھا، اور اگرچہ یہ مضحکہ خیز سا لگتا ہے، لیکن اب میں کام ختم کرکے کیفے پہنچنے کی جلدی میں ہوتا تھا کہ جلد از جلد اُسے دیکھ سکوں۔ یہی جگہ تھی جہاں سے اسے خوراک ملتی تھی۔۔۔ جو کچھ لوگ اسے دے جاتے تھے۔
چوتھے دن میں اسٹیٹ فارموں سے اپنی لاری سیدھا یہاں لے آیا۔میرا ننھا بچہ اُس وقت کیفے کی سیڑھیوں پہ ٹانگیں پسارے بیٹھا تھا اور دیکھنے میں ہی کافی بھُوکا لگ رہا تھا۔ میں نے کھڑکی سے سر باہر نکال کر اُسے آواز دی،
’’وانیاؔ!! ادھر آؤ! تمہیں گودام تک
جھولے دوں، پھر ہم یہیں واپس آ کر کچھ کھائیں گے!‘‘
میری آواز پر وہ لپکا اور دوڑ کر پائیدان پر چڑھ گی اور
کھڑکی سے اندر جھانک کر بولا،
’’آپ کو کیسے پتا چلا کہ میرا نام وانیاؔ ہے؟‘‘
اُس کی وہ پیاری سی آنکھیں
حیرت سے کُھل گئی تھیں۔ خیر میں نے اُسے بتایا ک میں اُن آدمیوں میں سے ہوں جنہیں
ہر بات کا پتہ ہوتا ہے!
وہ دائیں جانب سے گھوم کر آیا تو میں نے اُسے اندر،
اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ ہم چلے گئے۔ وہ بڑا زندہ دل بچہ تھا لیکن وہ اچانک خاموش ہو
گیا اور اپنی لمبی لمبی پلکوں کے نیچے سے مجھے گھور کر دیکھنے لگا۔ اُس نے ایک
ٹھنڈی آہ بھری۔ اتنی چھوٹی سی عمر میں اس نے آہ بھرنا سیکھ لیا تھا! یہ کام تھا
اُس کے کرنے کا؟
’’وانیاؔ! تمہارا باپ کہاں ہے؟‘‘
میں نے پوچھا۔
’’وہ محاذ پر مارے گئے تھے‘‘
اس نے سرگوشی کی۔
’’اور امّی؟‘‘
’’امّی دشمن کی بمباری میں مر گئی تھیں جب ہم ریل میں
سفر کر رہے تھے‘‘
’’تُم ریل میں کہاں سے آرہے تھے؟‘‘
’’پتہ نہیں، مجھے کچھ یاد نہیں!‘‘
’’اور تمہارا کوئی خاندان، گھر والے نہیں ہیں؟‘‘
’’نہیں، کوئی نہیں ہے!‘‘
’’تو تُم راتوں کو کہاں سوتے ہو؟‘‘
’’کہیں بھی۔۔۔ جہاں جگہ مل جائے‘‘
مجھے اپنے اندر گرم آنسوؤں کا ایک طوفان ابھرتا محسوس ہوا۔ اس لمحے میں مَیں نے ایک فیصلہ کر لیا۔ آخر کیوں ہم اکیلے اور جُدا جُدا زندگی کے دُکھ سہیں؟ میں اسے اپنا بیٹا بناؤں گا!۔ میں نے اپنے ذہن میں ایک طمانیت سی محسوس کی، دل و ذہن میں ایک اُجالا سا پھیل گیا تھا۔ میں اُس پر جُھک گیا اور دھیرے سے پوچھا،
’’وانیاؔ! تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟‘‘
اُس نے ایک لمبی سانس خارج کی،
’’کون؟‘‘
اور اسی دھیمی آواز میں مَیں نے اُسے کہا۔
’’میں تمہارا باپ ہوں!‘‘
خُدایا! پھر کیا ہوا! اُس نے اپنی بانہیں میرے گلے میں
ڈال لیں، میرے رُخساروں کو چوما، میرے ہونٹوں کو چوما، پھر پیشانی پہ اور کسی ننھے
پرندے کی طرح بہت بلند آواز میں چہچہانا شروع کر دیا،
’’پیارے ابّا!! مجھے معلوم تھا ! مجھے معلوم تھا آپ
مجھے ڈھونڈ لیں گے!! مجھے معلوم تھا، کچھ بھی ہو جائے، آپ مجھے ڈھونڈ لیں گے! میں
کب سے انتظار کر رہا تھا کہ آپ مجھے کب ڈھونڈ نکالیں !‘‘
وہ مجھ سے لپٹ گیا اور تیز ہوا میں پھڑپھڑاتے کسی پتّے کی طرح کانپنے لگا۔ میری آنکھیں ڈُبڈبا گئیں اور میں بھی کانپنے لگا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ خُدا جانے میں گاڑی کے اسٹیئرنگ وہیل کو کس طرح تھامے رکھا۔ پھربھی میں نے لاری ایک گڑھے میں دے ماری اور انجن بند کر دیا۔ میری آنکھیں اتنی ڈُبڈبا گئی تھیں کہ مجھے اندیشہ لاحق ہو گیا تھا کہ میں لاری سے کسی راہگیر کو ہی نہ کُچل بیٹھوں۔ ہم یہاں لگ بھگ پانچ منٹ بیٹھے رہے اور میرا ننھا سا بیٹا مجھ سے لپٹ کے کانپتا رہا۔ میں نے دائیں بازو سے اسے سینے سے لگا کر بھینچ لیا اور بائیں ہاتھ سے گاڑی چلاتا کر اپنے لکڑی کے گھر تک لے آیا جہاں میں رہتا تھا۔ اس کے بعد میں گودام نہیں جا سکتا تھا۔
میں نے لاری گھر کے
باہر کھڑی کی اور اپنے اس نئے بیٹے کو بانہوں میں اُٹھا کر اندر لے آیا۔ اُس نے
اپنی چھوٹی بانہیں مضبوطی سے میری گردن کے گرد حمائل کر رکھی تھیں۔ اُس نے اپنا
رُخسار میری بڑھی ہوئی شیو والے گال پر زور سے جما رکھا تھا۔ اسی حالت میں مَیں
اسے اندر اُٹھا لایا۔ میرا دوست اور اُس کی بیوی، دونوں گھر پر تھے، میں نے اُنہیں
دھیرے سے آنکھ ماری، پھر خوشی سے اعلان کیا،
’’بالآخر میں نے اپنے ننھے وانیاؔ کو تلاش کر ہی لیا!!
لو یہ رہے ہم!! اچھے لوگو!!‘‘
خود اُن کے ہاں بھی اولاد نہ تھی اور بچے کی خواہش تو اُنہیں بھی تھی، سو وہ صورتحال بھانپ گئے اور خوش ہو کر استقبال کرنے لگے۔ بچہ میرے بازوؤں کے گہوارے سے اُترنے کو تیار ہی نہ تھا! خیر، میں نے کسی نہ کسی طرح اُسے اُتار ہی لیا۔ میرے دوست کی بیوی نے اُسے بڑے پیار سے یخنی کی ایک پلیٹ دی اور جب دیکھا کہ بچے نے کس بے صبری سے اسے نگل لیا تھا، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ وہ چولہے کے پاس، ایپرن میں ملبوس کھڑی رو رہی تھی اور میرا وانیاؔ یہ دیکھ کر اُس کی طرف لپکا۔
’’آنٹی، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ ابّا مجھے
ڈھونڈ لائے ہیں، سب کو تو خوش ہونا چاہیئے!‘‘
جب وانیاؔ نے اُس کے دامن کو کھینچ کر کہا تو وہ مزید
بلبلا کر رونے لگ پڑی۔
شام کے کھانے کے بعد میں اُسے حجام کے پاس حجامت کیلئے
لے گیا، پھر گھر لا کر مَیں نے خود اسے نہلایا اور ایک صاف سفید چادر میں اسے لپیٹ
دیا۔ وہ مضبوطی سے میرے سیے سے لپٹا رہا اور اسی طرح میری باہوں میں ہی سو گیا۔
میں نے آہستگی سے اسے بستر پر لٹایا اور خود لاری لے کر گودام کی طرف چلا گیا۔
گیہوں کا بار اُتارنے کے بعد میں بازار گیا جہاں میَں نے اُس کیلئے ایک اونی پتلون
خریدی۔۔۔ اور ایک جوتوں کا جوڑا اور ایک تنکوں کا ہَیٹ بھی۔ یہ چیزیں لا محالہ طور
پر غلط سائز کی اور کم میعار کی نکلیں۔ میرے دوست کی بیوی نے پتلون دیکھ کر مجھے
ڈانٹ کر کہا،
’’پاگل ہو گئے ہو؟ اس گرمی میں اُونی پتلون پہناؤ گے
بچے کو؟‘‘
اسی لمحے وہ خاتون سلائی مشین لے کر بیٹھ گئی اور ایک گھنٹا مسلسل مشین چلانے کے بعد وہ میرے وانیاؔ کے لئے کاٹن کی ایک پتلون اور قمیص سی چُکی تھی۔ مَیں اُسے اُٹھا کر اپنے بستر پر لے گیا اور ایک مُدّت بعد پہلی بار پُر سکون نیند سویا۔ پھر بھی رات کو میں چار دفعہ جاگا، وہ کسی نوزائیدہ پرندے کی طرح میرے بازوؤں میں ہی لپٹ کے سویا نرمی سے سانس لے رہا تھا، جیسے کوئی چڑیا منڈیر میں دُبک کر سوئی ہو۔ میں اُن لمحوں کی مُسرت الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں کوشش کر رہا تھا کہ حرکت بھی نہ کروں، مبادا کہ اُسے زحمت ہو، لیکن پھر میں آہستگی سے اُٹھتا، ماچس جلا کے اُس کے پاس کھڑا ہوتا اور اُسے تحسین بھری نظروں سے دیکھتا۔
اگلی صبح مَیں مُنہ اندھیرے جاگا، پہلے تو کچھ سمجھ نہ آئی۔ مجھ پر یہ دباؤ سا کیسا ہے۔ یہ میرا کمسن بیٹا تھا۔ وہ اپنی چادر سے نکل کر میرے سینے پہ ترچھا سویا ہوا تھا اور اس کا ننھا سا پاؤں میرے حلق پر تھا۔ یہ لڑکا بھی ایک نادر قسم کی اُلجھن ہے ساتھ سُلانے کے حوالے سے! لیکن اب میں اس کا عادی ہو چکا ہوں۔ اب تو جب وہ میرے پاس نہ ہو میں اس کی کمی محسوس کرتا ہوں۔رات کو جب وہ سویا ہوتا ہے، میں اُس کو تھپکیاں دیتا ہوں، اُس کے گھنگریالے بالوں کی خوش بُو لیتا ہوں۔ اس طرح میرے دل میں بھرا کرب و غم نکل سا جاتا ہےاور میرا دل نرم پڑ جاتا ہے ورنہ آپ کو پتہ ہے، میں تو پتھر کا ہو چکا تھا۔
آغاز میں تو وہ میرے ساتھ لاری پہ سوار رہتا تھا لیکن پھر مجھے اندازہ ہوا کہ ایسا نہیں چلے گا۔ مجھے اکیلا رہنے میں تو پیٹ بھر نے کے لئے کچھ ذیادہ درکار نہ تھا، روٹی کا ایک ٹکڑا، ایک پیاز کی ڈلی، چٹکی بھر نمک کے ساتھ، مجھ فوجی آدمی کو سارا دن کافی تھی لیکن اس ننھی سی جان کے ہمراہ صورت حال مختلف تھی۔ اب ضرورت تھی کہ اس کے لئے کچھ دودھ کا انتظام ہو، اب اس کیلئے انڈے اُبالنا ضروری تھا اور گرم چیزیں کھائے بغیر اس بچے کا گزارا نہ تھا۔ مجھے بھی تو اپنا کام کاج کرنا ہوتا تھا۔ سو میں نے تھوڑی ہمت کی اور اسے اپنے دوست کی بیوی کی نگرانی میں دے دیا۔ وہ سارا دن روتا رہتا تھا اور شام ہوتے ہی گوداموں کی طرف دوڑ آتا اور رات گئے میرا انتظار کرتا۔
آغاز میں مجھے اس کے
حوالے سے کافی مشکلات رہیں۔ اب ہر مشقت سے بھرپور دن کے بعد دھندلکا ہوتے ہی ہم
سونے کیلئے چلے جاتے۔ وہ ہمیشہ چڑیوں کی طرح چہچہاتا رہتا لیکن ایک شام وہ خاموش
سا تھا۔
’’ابّا! آ پ کا وہ چمڑے کا کوٹ کیا ہوا؟‘‘
اُس نے چھت کو گھورتے ہوئے کہا۔
میرے پاس تو زندگی میں کبھی چمڑے کا کوٹ نہیں رہا تھا۔
لیکن اب اس سوال کا کچھ جواب تو دینا تھا۔
’’بیٹا وہ ورونزہؔ میں رہ گیا تھا‘‘
میں نے جواب دیا۔
’’اور آپ مجھے اتنے عرصے سے کیوں ڈھونڈ رہے تھے؟‘‘
اُس نے پوچھا تو میرا جواب تھا؛
’’بیٹا مَیں نے تُمہیں جرمنی میں ڈُھونڈا، پولینڈ میں
ڈھونڈا اور تمہاری تلاش میں بیلورشیا کا علاقہ چھان مارا اور تُم یوریاپنسک میں
ملے‘‘
’’ابّا کیایوریاپنسکؔ، جرمنی کے ذیادہ قریب ہے ہمارے گھر
سے؟ اور پولینڈ ہمارے گھر سے دُور ہے؟‘‘
ہم اس طرح کی باتیں کرتے کرتے سو گئے۔
کیا خیال ہے دوست؟ اُس نے چمڑے کے کوٹ کے بارے میں بے سبب پوچھا تھا؟ نہیں! یقیناً اس کی وجہ ہو گی ! اس کا مطلب یہ تھا کہ کبھی نہ کبھی اس کے حقیقی باپ کا کوئی چمڑے کا کوٹ ہو گا اور اس بچے کو وہ یاد تھا! بچے کی یادداشت ایسے ہے جیسے گرمی کے موسم میں آسمانی بجلی چمکتی ہے۔ پتہ ہے؟ یہ لشکارا سا مارتی ہے، لمحے بھر کو ہر چیز کو روشن اور عیاں کر کے بُجھ جاتی ہے۔ اس بچے کی یادداشت بجلی کے اس جھماکے کی طرح کام کررہی تھی جو گرما کی راتوں کو کڑکتی ہے۔
ہم لگ بھگ ایک سال یوریاپنسکؔ میں رہے ہوں گے لیکن پھر نومبر میں میرے ساتھ ایک حادثہ ہو گیا۔ میں ایک گاؤں میں کیچڑ سے بھرے راستے پر لاری چلا رہا تھا کہ وہ پھسل گئی۔ راستے میں ایک گائے موجود تھی جو گاڑی کی ذ د میں آگئی۔ آپ کو تو پتہ ہے پھر کیا ہوتا ہے، عورتوں نے وہ کہرام مچایا کہ وہاں اچھا خاصہ مجمع اکٹھا ہو گیا اور آن کی آن میں ایک ٹریفک انسپکٹر بھی وہاں آ دھمکا۔ مَیں نے اُس کی سماجت تو کی لیکن اُس نے میرا ڈرائیونگ لائسنس ضبط کرلیا۔ گائے اسی اثنأ میں اُٹھ کھڑی ہوئی، ہوا میں اپنی دُم لہرائی اور سرپٹ دوڑتی ہوئی گلی میں غائب ہو گئی لیکن میرا ڈرائیونگ لائسنس میرے ہاتھ سے جا چکا تھا۔ موسمِ سرما تو مَیں نے کنڈکٹری میں گزارا لیکن پھر اپنے ایک فوجی دوست سے رابطہ کیا جو آپ کے ضلعے میں ڈرائیور ہے۔ ہمارے علاقے میں ایک سال کنڈکٹری کے بعد ڈرائیونگ لائسنس مل جاتا ہے۔ سو اب مَیں اور میرا بیٹا کاشاریؔ روانہ ہوئے۔
اگر وہ گائے والا حادثہ نہ بھی ہوتا تو میں تب بھی یوریاپنسکؔ چھوڑ دیتا کیونکہ میں ایک جگہ ذیادہ عرصے کے لئے نہیں رہ سکتا۔ تاہم اُمّید ہے کہ جب میرا وانیاؔ بڑا ہو کر اسکول جانے لگا تو میَں ایک جگہ ٹِک کر محنت کرنے لگوں گا۔ لیکن سرِ دست ہم دونوں اکٹھےرُوسؔ کی سر زمین اپنے آوارہ گرد قدموں سے ناپ رہے ہیں۔
’یہ تھکتا نہیں ہے؟‘ میں نے پوچھا۔
نہیں، یہ ذیادہ دیر پیدل نہیں چلتا، بیشتر وقت میرے شانوں پر سواری کرتا ہے۔ مَیں اسے سواری پیش کرنے کے لئے اپنے کاندھے جھُکا دیتا ہوں۔جب اس کا جی چاہتا ہے کہ ذرا ٹانگیں سیدھی کر لے، یہ نیچے پھلانگ جاتا ہے اور سڑک کنارے دوڑنا یا کسی ننھے سے میمنے کی طرح خوشدلی سے ادھر اُدھر ٹہلنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہے دوست، کہ سب اسی طرح ٹھیک چلے گا۔ مجھے اپنے دلی قویٰ پر بھروسہ نہیں رہا۔ جیسے اب اس دل کا ’پسٹن‘ بدلنے والا ہو گیا ہو۔ کبھی کبھی دل یوں ڈوبتا ہے کہ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جاتا ہے۔ مجھے تو ڈر ہے کہیں کسی دن میں نیند کے دوران ہی ابدی نیند سو جاؤں گا اور میرا بیٹا مجھی سے ڈر جائے گا۔ صرف یہی نہیں، جو مجھ پر بیت رہی ہے۔۔۔ کم و بیش ہررات میں خوابوں میں اپنے اُن پیاروں کو دیکھتا ہوں جنہیں میں کھو چکا ہوں۔ اور اکثر اس طرح کہ میں کسی خاردار باڑ کے اندر کی جانب ہوں اور وہ باہر ہیں، آزاد ہیں۔ میں ارینہؔ سے ہر موضوع پر باتیں کرتا ہوں اور بچوں سے بھی لیکن جونہی میں اس خاردار باڑ کو ہٹانے کی کوشش کرتا ہوں، وہ سب کہیں دُور چلے جاتے ہیں، جیسے میری آنکھوں کے سامنے پگھل گئے ہوں۔ ایک اور مزے کی بات! مَیں سارا دن خود پہ کمال ضبط کئے رکھتا ہوں، اتنا کہ آپ میری سرد آہ تک نہ سُنیں گے لیکن راتوں کو میں اکثر جب نیند سے چونک اُٹھتا ہوں تو میرا تکیہ آنسوؤں سے تر ہوتا ہے۔۔۔‘‘
دریا کی جانب سے میرے دوست کی آواز سنائی دی اور ساتھ ہی پانی میں چپوُ چلنے کی آواز بھی۔۔۔ اس اجنبی نے، جو اب میرے لئے ایک قریبی دوست جیسا تھا، اپنا مضبوط ہاتھ مصافحے کے لئے بڑھایا۔
’’الوداع دوست! سلامت رہو!‘
’’سلامت رہو! کاشاریؔ کیلئے سفر بخیر!‘‘
’’ شُکریہ۔۔۔ بیٹا آؤ کشتی کی طرف!‘‘
بچہ اُس کی طرف لپکا اور اپنے باپ کے کوٹ کا کونا تھا،
اس کے ساتھ ننھے ننھے قدموں سے چل دیا۔
دو یتیم، ریت کے دو ذرّے جنہیں جنگ کے بے پناہ طوفان نے دو اجنبی سمتوں میں بکھیر دیا تھا، اب ان کی تقدیر میں اَور کیا کچھ تھا؟؟ مجھے ایک بات کا یقین تھا کہ یہ روسی، یہ ناقابلِ شکست عزم والا آدمی ہر حال میں نباہے گا اور یہ بچہ اپنے باپ کے نقشِ قدم پر پروان چڑھے گا جو مادرِ وطن کے بُلاوے پر کوئی بھی کڑا وقت گزار جائے گا، کسی بھی رکاوٹ کو عبور کر جائے گا۔۔۔
میں انہیں جاتا ہوا دیکھ کر اُداس ہو گیا۔ شاید ان سے جُدا ہونا آسان ہوتا اگر وانیاؔ چند قدم چلنے کے بعد اپنے ننھے سے قدموں پر مُڑ کر اپنا پھول جیسا نازک ہاتھ ہِلا کر مجھے الوداع نہ کہتا۔ اچانک مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نرم سے پنجے نے میرا دل دبوچ لیا ہو۔ مَیں نے تیزی سے ایک طرف مُنہ پھیر لیا۔ یہ بوڑھے لوگ جن کے سَر جنگ کے کٹھن سالوں نے سفید کر دئیے ہیں، صرف راتوں کو نیند میں ہی نہیں روتے بلکہ دن کی بیداریوں میں بھی روتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ آدمی بر وقت مُنہ ایک طرف پھیر لینے کے قابل ہو۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ ایک بچے کا دل نہ دُکھنے دیا جائے! اُسے وہ بے اختیار آنسُو نظر نہ آنے دیا جائے جو کہ ایک مرد کے رُخساروں کو بھی جلا دیتا ہے!!!
( ترجمہ زکی نقوی )